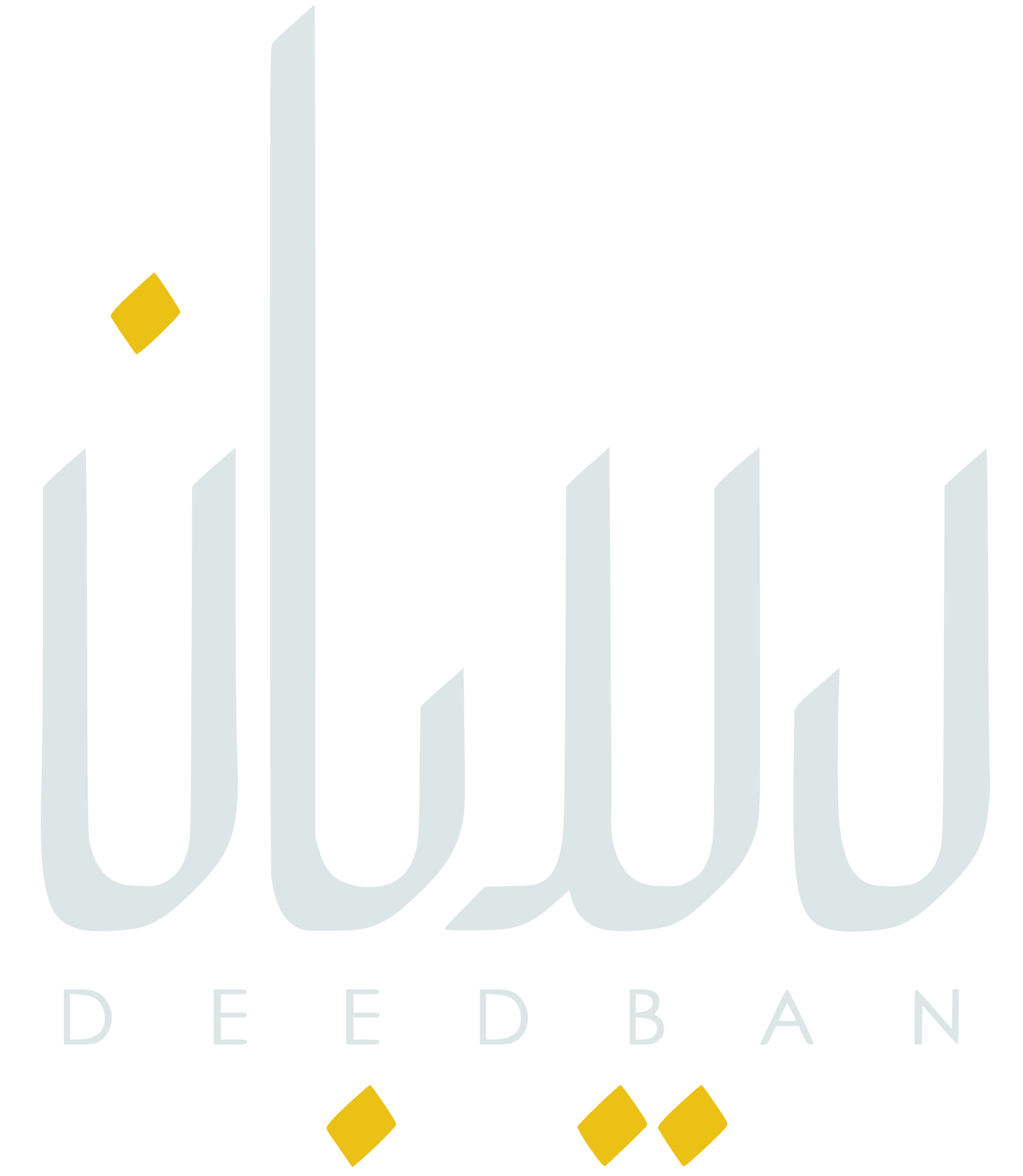ناول پس غبار سفر
ناول پس غبار سفر
Mar 13, 2018

دیدبان شمارہ ۔۷
ناول پس غبار سفر
مصنف خالد قیوم تنولی
آخری قسط
(١١ )
!خانم
ٹھیک تین دن بعد ہم نے گھر کی چابیاں خدیجہ کے حوالے کر دیں۔ یہ
تجویز بھی مریم کی تھی۔ بہ قول اس کے خدیجہ کو ہمارے گھر کا محلِ وقوع بہت بھاتا
تھا کیوں کہ اس کی مماثلت اسے اپنے اطالیہ کے آبائی علاقے، گھر اور بالپن کی یاد
دلاتی تھی۔ وہ طرب زار یاد آفرینی کی پریشان تتلی ایک بوئے گرفتار تھی مگر یہ جان
کر کہ زیست کے باقی ماندہ ایام سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے کے لیے ہم اس کے حضور
میں وہ نذر گزر رہے ہیں جو اسے مرغوب تھی تو وہ سیراب روح ہمارے بے حد اصرار کے
بعد رضا مند ہوئی اور ہم نے اس کی پیرانہ آنکھوں کو دیکھ کر جانا کہ ویران مزاروں
پر جلتے ہوئے چراغ کیوں اتنے بھلے لگتے ہیں ۔ روشنی زندگی کا استعارہ ہے۔ زندگی
احساس ، شوق اور درد بھی ہے۔ جو کچھ بھی تھا نہ ہمارا اور نہ ہی مستقل خدیجہ کا
رہنے والا تھا۔ لافانی تو وہ جذبہ تھا جو تھوڑی دیر کے لیے سہی اسکی روح میں وسعت
بھر رہا تھا اور اس کی عمر رسیدہ مسکراہٹ کو اداس سی شوخی دے رہا تھا اور اس کے
جذباتِ تشکر سے کپکپاتے لہجے کو مسرت سے نواز رہا تھا۔
رخصت ہونے سے قبل آمنہ نے اسے ایک چھوٹی سے پوٹلی بھی تھما دی۔
’’یہ کیا ہے؟‘‘
’’آپ کے خواب کی تعبیر‘‘
’’کیسی تعبیر؟‘‘
’’آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منّورہ کی
زیارت کی متمنی جو ہیں ‘‘
’’مگر اس کے لیے تو پس انداز کر رہی
ہوں ۔ یہ میں نہیں لوں گی‘‘
’’میں کون سا اپنے پاس سے دے رہی ہوں۔
یہ تو امانت ہے جو آپ تک پہنچانا میرا فریضہ تھا‘‘
’’سبحان اللہ ۔ جس نے حاضری کی التجا
قبول کی وہی اسبابِ سفر بھی عطا کر رہا ہے‘‘۔
’’بے شک خدیجہ جی۔۔۔ اور اس سے بھی
بڑھ کر وہ تسکینِ قلب ہے جو آسائشِ ہستی کی دلیل ہے‘‘
’’ہاں ۔۔۔ ہاں۔۔۔۔ اصل سرمایہ تو یہی
ہے۔ دل کی امیری کا اب خوب اندازہ ہُوا‘‘
’’جب آپ وہاں حاضر ہوں تو ہمارے لیے
رحمت اور بخشش کی دعا کرنا نہ بھولیئے گا‘‘
’’’’ضرور۔۔۔ ضرور۔۔۔۔‘‘ خدیجہ رونے
لگیں اور روتے روتے انہوں نے اپنی بانہیں واکیں ۔ اتنی واکیں کہ ہم تینوں ان کی
وسیع اور اعلیٰ ظرف آغوش میں سمٹ گئے۔ ان کی ہچکیاں بلند ہو گئیں ۔ پتہ نہیں کب
مائی خیراں بھی آگئیں اور اپنی پیوندزدہ اوڑھنی کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھنے
لگیں ۔
ان نم دیدہ ساعتوں میں دونوں بزرگ خواتین سے ہم نے اذنِ رخصت لیا
اور اپنے عقب میں آباد بستی کی رونقوں کو چھوڑ کر ندی کی جانب اترتے راستے پر ہو
لیے۔
کھیتوں میں دہقان مرد اور عورتیں کا م میں مصروف تھیں اور سورج
ان کے سروں کے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت سے ہاتھ پیشانیوں تک اٹھے اور وداعی انداز
میں لہرائے۔ جواباً ہم نے بھی یہی کیا۔ اس ادا میں دوستی ،بے تکلفی، دلبری، خلوص
اور اپنائیت کے رنگ تھے اور ہمارے دل و دماغ پر ان ہی رنگ بہ رنگ جلوؤں کا جمگھٹ
تھا۔ کچھ دیر کی اس دیدنی چاہت نے پر چھائیں ہو جانا تھا۔
چلتے چلتے ہم ندی کے اس پاٹ پر جا کھڑے ہوئے جہاں ہماری عمروں
کے کثیر لمحے بیتے تھے۔ سولہ برس کی مدت ایک دم سے نظروں میں گھوم گئی۔ سفر آگے کا
ہو یا پیچھے کا کوئی نہ کوئی دریا حائل ہو ہی جاتا ہے مگر نشانِ سوال ہو یا رکاوٹ
تا دیر حائل نہیں رہتی۔ صرف احتسابِ یاد در پیش ہوتا ہے۔ تہذیبوں کے میلے ہوں یا
یادوں کے جھمیلے، کنارِ آب ان کی رونق کئی چند ہو جاتی ہے ۔
نورو ملاح کی ناؤ ندی کے اس پار سے واپس پلٹ رہی تھی ۔ گمبھیر
ترنم میں گنگناتے بوڑھے ملاح کی دبنگ لَے ہم تک پہنچ رہی تھی:
’’عیشِ منزل ہے غریباںِ محبت پہ حرام
’’سب مسافر ہیں بہ ظاہر نظرآتے ہیں
مقیم‘‘
ناؤ دھیرے دھیرے کنارے تک پہنچی تو میں نے مضمحل شائستگی سے
کہا: ’’اے ساکنِ وادئ دلدار ہم چلے۔۔۔۔۔‘‘ نورو ایک با وقار اور دل گرفتہ ہنسی
ہنسا اور پتوار چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے سر تھام ، ہمیں اپنی نگہہ کے محیط میں لا
کر بولا:’’ تو پھر یہ طے ہے کہ تم لوگ جا رہے ہو؟‘‘
’’ہاں بابا!‘‘
’’واپس آؤ گے؟‘‘
’’خدا بہتر جانتا ہے‘‘
’’سجنو! میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ بانکا
سجیلا۔ فوج کا سپاہی۔ محاذ پر گیا۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو آنکھ
سے باہر کبھی نہیں جھانکتے۔ میں نے واپسی کی امید اس کے تیوروں میں کھودی۔ کوئی
مہینہ بھر بعد جنگ تھم گئی۔ ڈاک کا ہر کارہ آیا اور تار دے گیا کہ جس کا ذکر تمہیں
ہر شے سے پیارا تھا وہ دشمن کی زمین پر دشمنوں کے نرغے میں کام آگیا ہے۔ جس کا مال
تھا اس نے واپس لے لیا۔ اللہ کی مرضی برحق مگر جو یہ دل ہے، یہ تو روتا ہے۔ سو میں
بھی رویا۔ بہت دنوں تک روتا رہا۔ اس کی ماں بھی روتی رہی مگر باہمت عورت تھی۔ ایک
دن میرے جھکے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی: ’’مت رو نُورو۔
آنکھیں بے نور ہو جائیں گی ۔ میں کہاں سے تیرے لیے قمیضِ یوسف لاؤں گی۔ مت رو
نورو‘‘۔ میں نے آنسو پونچھے۔ پتوار سنبھالے۔ ناؤ میں آبیٹھا۔ آؤ بیٹھو مسافرو۔۔۔۔!‘‘
ہم ایک دل گیرا حساس سمیت نورو کی الم نصیب فراست سے لاجواب ہو
کر ناؤ میں سوار ہوئے۔ اس نے چپو تھامے اور ناؤ کا رخ پھیرنے لگا۔ ناؤ نے چکر کاٹا
اور ایک لمحاتی ساگر داب بنا کر متعینہ جانب آگے بڑھنے لگی۔
’’زندگی اور موت کا فلسفہ میں نے ان
ہی دو کناروں کے درمیان سے سیکھا ہے فہیم!‘‘ نورو نے سلسلۂ کلام جوڑتے ہوئے کہا:
’’کبھی نہیں ملتے یہ دونوں ۔ مل جاتے تو روانی نے کب باقی رہنا تھا۔ درمیان میں
وقت بہتا ہے۔ سارے بھنور، تلاطم ، ہمواری اور سکون وقت کے تابع ہیں ۔ انسان تو صرف
چپو چلاتا ہے۔ وجود کی کشتی کو متحرک رکھنے کے لیے ۔ اتنا ہی اختیار حاصل ہے ہمیں۔
درمیان میں رہ کر وقت کے ساتھ بہتے رہنا ہی مقدر ہے۔ کناروں سے باہر نکلنے کا
فیصلہ کسی اور کے پاس ہے۔ حکیم انصاری کو اتنی سامنے کی بات بھی دکھائی نہیں دیتی
۔ کملا کہیں کا۔ اور تم لوگ جا رہے ہو ایں؟۔۔۔۔ غالباً تیسری یا چوتھی مجلس تھی۔
مریم تُونے بیٹاایک نغمہ سنایا تھا۔ یاد ہے ناں؟۔۔۔ ہوجائے پھر آخری بار۔۔۔۔ سنا
دو میری سوہنی سجنی!‘‘
’’جی باباجی۔۔۔ سناتی ہوں ‘‘
’’اوئے زندہ باد ۔۔۔ بسم اللہ ۔۔۔ بسم
اللہ‘‘
مریم نے ایک بار ہمیں جھینپ کر دیکھا اور ہمارے تائیدی انداز سے
مطمئن ہو کر آنکھیں موندلیں اور ننھی منی لہروں کے سنگ اس کی مدھر آواز کا جادو
بھی بہنے لگا:
’’یہ جلوؤں کی تابانیوں کا تسلسل
یہ ذوقِ نظر کا دوام اللہ اللہ ‘‘
اور خانم ! میں آپ کو سوچنے لگا ۔ ان گنت صدیوں پر پھیلے ہجر کی
دھندچھُٹنے لگی اور دُور افق پر آپ کی وجود کی شبیہ طلوع ہونے لگی۔ مدتوں پہلے کا
دیکھا ہوا آپ کا شفیق سراپا مثلِ آفتاب میرے سامنے تھا۔ رنگوں ، خوشبوؤں ، خوابوں
اور لفظوں کی حد سے آگے تک ہمہ گیر ہوتا محسوس ہوا۔ لگا جیسے لپک کر آپ کے قدم چھو
لوں گا۔ سچ کہا تھا کسی کہنے والے نے کہ بعض بیج جو ایک بار خون اور گوشت میں اپنا
اکھوا ابھارنے میں کامیاب ہو جائیں تو چاہے کیسے ہی طوفان آئیں اسے جڑ سے نہیں
اکھاڑ سکتے۔ بانسوں کے جنگل کی طرح جڑوں کی شریانیں بکھیردیتے ہیں ۔ روح میں گھل
مل جاتے ہیں ۔
’’وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم
وہ آبِ رواں بے خرام اللہ اللہ‘‘
مریم کی آوازاثر پزیری کے ساحل سے جاملی اور ناؤ کنارے سے ۔ میں
نے کچھ روپے بابا نورو کو دینے چاہے تو اس نے نفی میں سر ہلایا: ’’افسوس تُوہر بار
بھول جاتا ہے فہیم۔ کرایہ میں کسی سے بھی نہیں لیتا۔ کبھی نہیں لیا۔ یہ تو کسی کا
حکم ہے جس کی بجا آوری کا وعدہ تادمِ مرگ نبھاتا رہوں گا۔ رزق کا وعدہ بھی پورا
ہوتا آرہا ہے۔ رکھ ان پیسوں کو اپنے پاس۔ تیرے کام آئیں گے‘‘ یہ کہہ کر اس نے
پتوار چھوڑے، اٹھا اور مجھے گلے سے لگالیا۔ آمنہ کے سر پہ دستِ شفقت پھیرا اور
مریم کی پیشانی کے بہت سے بوسے لیے۔ دعائیں دینے لگا۔
آمنہ بولی: ’’فاصلے، مرحلے اور راہوں کی جدائی بے معنی ہوتی ہے
بابا۔ ہمارے دل ملے ہیں تو اوجھل ہونے کا صدمہ بے حیثیت ہے۔ کلفتِ حیات ہیچ اور
آشوبِ غمِ مرگ ایک سائے کی مانند ہے۔ سدا کب ایک سے لیل ونہار رہتے ہیں ۔ ۔۔ جس
طرح اس بہتے پانی کی ایک یقینی منزل ہے بالکل ویسے ہی مسافت کی بھی۔ سفر سہانا ہو
یا کٹھن تمنا یہ ہو کہ جو منزل ملے وہ نجات آفریں ہو۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا‘‘
’’خدا حافظ میری بچی۔۔۔ خدا حافظ!‘‘
’’خدا حافظ بابا۔۔۔۔‘‘
ہم تینوں سر کنڈوں کے جھنڈوں میں سے گزرنے لگے اور اس جنگل کے
قریب ہونے لگے جس کے بھیدوں کی اوٹ سے بانسری کی لَے سنائی دیا کرتی تھی۔
کئی سچ ایسے ہوتے ہیں خانم! جنھیں سمجھنے کے لیے دریا عبور کرنا
پڑتا ہے۔ جو سکون کی کیفیت میں صدیوں سجھائی نہیں دیتے وہی جدائی کے وقت اپنی تمام
قوت اور سنگینی کے ساتھ ابھر آتے ہیں ۔ فاصلوں ، مرحلوں اور راستوں کی علا حدگی،
قرار اور جمود میں کبھی نہیں کھلتی لیکن فیصلے کی ندی کے پار عیاں ہوتی ہے۔ کہتے
ہیں سدہارتھ جیون کا میلہ چھوڑ کر گیان کی کھوج میں نکل گیا۔ برسوں گزار دیئے۔
واپس آیا تو بیوی نے پوچھا: ’’جو اتنے برسوں میں سیکھا کیا گھر میں ممکن نہ تھا؟‘‘
سدہارتھ جواب میں بڑے اسرار بھرے انداز میں مسکرایا: ’’ممکن تو
تھا مگر سمجھ میں کبھی نہ آسکتا۔ جوگ ضروری تھا‘‘
بعض تجربات عامیوں اور خواص کے یکساں ہوتے ہیں ۔ خوشی کے ساتھ
دردوسوز کی تخلیق بھی جب تک خود نہ کی جائے تو یہ آپوں آپ کبھی نہیں ملتے ۔ جوگ
بنا روگ کی لذت کسی دکان سے مول نہیں ملتی۔
چلتے چلتے میں نے تو اپنے آپ سے کہا تھا کہ خدا جانے نورو بھی
کس راز سے بھرا ہوا آدمی ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی: ’’مسافر ہے اپنے سفر کی دھن میں
کھویا ہوا۔ نہ اس دنیا پر قانع اور نہ ہی اخروی نجات کے لیے فکر مند۔ ایسے لوگ
سراسررضا ہوتے ہیں ۔ خالصتاً قدرت کے لیے مختص۔۔۔۔ انہیں ایک ہی بار آزمائش کی
بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا جاتا ہے۔ ساری بے قراری، اذیت، پشیمانی، خوف، ملال،
بھوک، مرض، کیف اور مسرت کا ذائقہ چکھ کر ان کا من شانت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اپنے
بھی نہیں رہتے۔ اسی کے ہو جاتے ہیں جو جس کا ہو جائے تو کسی اور کا نہیں ہونے دیتا‘‘
ہم جنگل کی شروعات میں چلے جا رہے تھے۔ خنکی گہری ہو رہی تھی۔
پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں میں سے گزرتی ہوا کی بہ دولت پتوں کی تالیوں کی
دھیمی دھیمی آواز تھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ فضا کی خوشگواری اور من کی بے کلی کے
امتزاج سے بہ خوبی آگاہ ہم تینوں ترچھی راہ پر اوپر ہی اوپر گامزن رہے۔ حتیٰ کہ وہ
مقام آیا جہاں میں نے ایک کُبڑے دریوزہ گر اور نوخیز دوشیزہ کو محوِ گفتگو دیکھا
تھا۔ دریوزہ گر کی کوئی خبر نہ تھی مگر نوخیز دوشیزہ میرے پیچھے خراماں خراماں چلی
آرہی میری بیٹی تھی۔ بھیدوں بھری ، پُر عزم اور بہ یک وقت نگاہ و قیاس کو
جھٹلادیئے جانے والے تصور پر قادر۔ میری دل کی تہہ سے سوال اٹھا ۔ میں نے چاہا کہ
اس سے پوچھوں ۔ کُبڑا دریوزہ گر کہاں گیا؟ مگر اس کی بے پناہ چُپ اور آمنہ کی وضاحت
کے سبب میں باز رہا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(١٢)
واپسی کا سفر بڑا طویل مگر زادِ راہ ناگزیر ، مختصر اور ہلکا
ہونے کی بہ دولت بڑی سہولت سے کٹتا رہا۔ بہت سے نظارے ہدفِ نظر رہے۔ چھُوٹے ہوئے
مقام کا احساس مسافروں کو ہر گام پر اداس کرتا رہا۔ اپنائیت کے حلقے سے باہر نکل
جانے اور مسلسل دور ہوتے چلے جانے کے خیال نے دل کو متواتر جکڑے رکھا۔ ہماری ہجرت
سائبیریائی مہاجر پرندوں جیسی تو نہ تھی کہ پلٹ کے جانے کے بہلاوے سے خود کو مطمئن
رکھ پاتے۔ پیڑطائروں کی مفارقت سے سوکھ نہیں جاتے۔ چند شائقین کے چلے جانے سے میلہ
اُجڑ نہیں جاتا۔
متحر ک زندگی دیرینہ بام ودر کو پھرسے دیکھنے کے لیے لوٹ رہی
تھی۔ عجیب کیفیت سی طاری ہونے لگی۔ میں بچہ بن گیا۔ بھولے بسرے فسوّں خیز واقعات
تحت الّشعورسے خود کو دہرانے کی غرض سے چشمِ وا کے سامنے آنے لگے ۔ بیتی ہوئی
زندگی کے ان ٹکڑوں کو دیکھنا عذاب نہ لگا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ انہیں روکنا محال تھا۔
مریم اس دوران اپنے مشاہدات مجھ سے بانٹ رہی تھی لیکن میں وہاں ہوتا تو اسے جواب
دیتا۔ وہ نہیں جان پائی کہ میں یادآفرینی کے بلیک ہول سے گزر رہا ہوں جس میں وقت
بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ دورانیہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور میں اپنے حال میں لوٹ
آیا۔
ہماری بس دریا کنار کے کی سیاہ تارکول والی سڑک پر رواں تھی۔ ہر
منظر لپک کر آتا اور کھلی آنکھوں کے رستے دل و دماغ میں اتر جاتا۔
میدانی وسعتیں جن میں خود روگھاس لہراتی تھی۔ بے ثمر اشجار بازو
اٹھائے کھڑے تھے۔ بے ترتیب مکانات اور افتادگانِ خاک کی متنوع صورتیں تھیں ۔۔۔ بس
کبھی کبھی پُر ہجوم آبادیوں میں سے گزرتی تو بھرے بازار اور ان سے ملتی آنتوں جیسی
پُر پیچ گلیاں دکھائی دیتیں ۔ اسبابِ زیست سے بھری دکانوں کے چھجے ، باغات،
میناروں سے گونجتی دعوتِ فلاح کی صدائیں ، مختلف زبانوں کی موسیقی، کہیں دھوپ اور
کہیں گھنے بادل ، بارش ، کوہستانی سلسلے پر پھیلے وسیع و عریض جنگلات، ماہر چھاتہ
برداروں کی مانند زمین پر اُترتے شام کے دھندلکے ، کروڑوں ستاروں کی متحدہ لَو سے
بھی نہ ٹلنے والی تاریکئ شب ۔۔۔ خیمۂ فلک کے نیچے سُبک رَو ہوائیں، پہاڑی نالے اور
ہماری بس متحرک تھی۔۔۔۔ اور میرا خیال بھی جو نا معلوم منطقوں سے ہوتا ہوا آپ تک
جا پہنچا ۔ مگر آپ کہاں تھیں ؟ ۔۔۔۔ آپ کو تصور کرتے ہوئے نا گاہ نظر اس بند
دروازے پر ٹھہر گئی جس پر عبارت درج تھی۔
’مکان فروخت ہو چکا ہے‘‘
میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آمنہ اونگھ رہی تھی ۔ اس کی لامبی سیاہ
پلکیں چینی پگوڈے کے چھجے کی مانند بند آنکھوں پر پڑی تھیں ۔ میں نے اس کے اندازِ
بے خبری کو بے حد اپنائیت سے دیکھا ۔ اس عروسِ دل کے گداز گالوں پر گردِ سفر کے
آثار تھے۔ میں دید کے اس بار کو تا دیر نہ اٹھا سکا کیوں کہ بس طعامِ شب کے واسطے
کسی سرائے کے باہر رک چکی تھی۔ تمام مسافر اتر گئے۔ یہ کوئی پرانے طرز تعمیر کی
حامل عمارت جس میں پتھر اور لکڑی کا بے دریغ استعمال ہُوا تھا۔ بدھ مندروں جیسی پر
اسرار اور پُر امن ۔ ہم یخ بستہ پانی سے ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہوئے ۔ ایک عمر
رسیدہ ملاز م نے احاطۂ سرائے کے ایک الگ تھلگ اور پر سکون گوشے تک ہماری رہنمائی
کی جہاں نہایت خوبصورت منقش لکڑی کی میز اور کرسیاں بچھی تھیں ۔ گیروے رنگ میں
ملبوس ایک بدھ بھکشو پہلے سے براجمان اپنے سفید چینی مٹی کے نقش و نگار والے
چاولوں سے بھرے پیالے سے شغل کر رہا تھا۔ داڑھی، مونچھیں ،بھنویں اور سر کے بالوں
سے قطعی آزاد۔ پاؤں میں چمڑے کے ہلکے اور سادہ چپل اور گلے میں خوش رنگ مالائیں ۔
اس کی لمبی مخروطی انگلیاں بے حد شائستگی اور نفاست سے نوالوں کو پیالے سے منہ تک
پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہی تھیں ۔ ہم تینوں بیٹھ چکے تو اس نے بڑی صلح جُواور بے
داغ مسکراہٹ سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ جواباً ہم بھی خوش خلقی سے مسکرائے ۔ ہمارے
قدموں کے نیچے دریائی گول سنگریزے بچھے تھے۔ آس پاس کے ماحول میں نمی ، خوشگوار
خنکی اور دھیمی دھیمی دھند سی چھائی تھی۔ آرام دہ نشستوں نے سفر کی تکان کو بہلا
پھسلا کر جانے کہاں بھیج دیااور ہم سہولت محسوس کرنے لگے تھے ۔ تھوڑی دیر بعد
ہمارا کھانا میز پر چُن دیا گیا۔ یہ اُبلی ہوئی سبزیوں ، یخنی، دلیے، چپاتی، چٹنی،
سلاد اور تازہ پھلوں کے عرق پر مشتمل تھا۔ کھانے کی شروعات میں بھکشو کو بھی دعوت
دی گئی جسے اس نے متشکر انہ انداز سے ٹال دیا۔ تاروں کی چھاؤں ، ہوا کے لطیف
جھونکوں اور تاریکی کی لپٹوں میں اس سفری طعام نے خوب لذت دی۔
مریم ، بھکشو کو دلچسپی سے دیکھے جا رہی تھی۔ دفعتاً بولی:
’’کیا مزے کی آزاد زندگی جی رہا ہے یہ آدمی۔ ہے نا بابا؟‘‘
’’ہاں بیٹا‘‘ میں نے کن اکھیوں سے
بھکشو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ’’زندگی ضرورت کی طرح گزارنی چاہیے۔ خواہش کی طرح
نہیں ۔ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں
ہوتی‘‘َ
آمنہ نے کہا : ’’آرزو سے بے نیازی، وقت کی المناکیوں سے باہر لے
جاتی ہے۔ غیر ضروری تقاضوں سے جی فرار چاہتا ہے اور جسم کے خس و خاشاک ساتھ چھوڑ
دیتے ہیں ‘‘
ہم سمجھے کہ وہ بھکشو ہماری گفتگو کو سمجھنے سے قاصر ہو گا مگر
وہ مسکرایا، دھیرے سے کھنکارا اور بولا: ’’آپ کی باتوں میں مخل ہونے کی جسارت پر
معافی چاہتا ہوں‘‘
ہم اکھٹے ہنس پڑے اور اسے خوش آمدید کہا۔
بھکشو بولا: ’’میں آپ سے متفق ہوں ۔ چند برس ہوئے یونیورسٹی کی
پروفیسری کو خیر آباد کہے ہوئے۔ من اُکتا گیا تھا مصنوعی زندگی جیتے جیتے ۔ جب سے
دنیا کو چھوڑا ہے جی بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تیاگ کا سفر مزید کتنی دیر جاری رہے۔
نہیں جانتا ۔ بس ہمہ وقت حرکت میں ہوں ۔ قرطاسِ جہاں طویل تر ہے اور لگتا ہے ابھی
تمہید بھی ختم نہیں ہوئی ‘‘
’’تیاگ کی مقصدیت کیا ہے؟‘‘ میں نے
پوچھا۔
’’تلاشِ حق‘‘
’’اپنے بارے کچھ مزید بتائیے‘‘
’’نسلاً تبتی ہوں ۔ پیدائش بھارت میں
ہوئی۔ تعلیم کا عرصہ اور جوانی نیپال میں گزری جب کہ ملازمت چین میں کی۔ پیکنک
یونیورسٹی میں ہندی زبان پڑھاتا رہا۔ مجھے آپ کوئی بھی نام دے لیں ۔ اب عام اور گم
نام رہنے پر اکتفا کر چکا ہوں ۔ مکتی پانے کے لیے مشہور و معروف ہونا ضروری تو
نہیں ناں۔۔۔۔ شہرت کی مدرا میں مست رہ کر کچھ بھی نہیں ملا۔ جُز کی اوقات ہی کیا
ہوتی ہے۔ اب کُل میں جذب ہونے کے سوم رس سے عیش کرنے کی ٹھانی ہے۔ آسائشات کی ہوس
بڑی راکھشس ہوتی ہے جناب۔ یہ بھید بڑی دیر بعد بُدھی میں سمایا ہے ۔ خیر یہ وقت
طلب باتیں ہیں ۔ کچھ دیر کا ساتھ ہے۔ کہیں آپ کو بیزار نہ کر دوں ۔۔۔۔‘‘
’’نہیں نہیں ۔ ایسا مت سوچیں ۔ آپ
ہمیں اچھے لگے ہیں ‘‘
’’شکریہ۔۔۔ اور آپ بھی تو بتائیے اپنے
متعلق‘‘
’’میں فہیم ہوں ۔ یہ آمنہ ہیں ، میری
جیون شریک اور وہ ہماری بیٹی ہے، مریم
‘‘
’’بھکشو نے دونوں کو تین بار سر جھکا
کر تعظیم دی اور اپنی بے داغ اور نستعلیق مسکراہٹ سے خوش وقت کیا۔
’’کیا تیاگ ضروری ہے؟؟‘‘ مریم پوچھے
بغیر نہ رہ سکی۔
’’یقیناًضروری ہے‘‘ بھکشو نے اپنی
مسکراہٹ کو طول دیتے ہوئے کہا۔ ’’جب من بے کل ہو توجانتی ہو کیا ہوتا ہے ؟ اچھا یہ
بتاؤ جب بے تابی ہو تو انسان اپنا مقام کیوں بدلتا ہے۔ یعنی کمرہ چھوڑ کر باہر
کیوں آجاتا ہے ۔ جواب کے لیے تیاگ ضروری ہے ۔ قرار کے لیے لازمی ہے ۔ عظیم بُدھانے
تیاگ کے کارن ہی نروان پایا اور تتھاگت بنے۔ آپ لوگ مسلمان ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ
آپ کے پیغمبر حضرت محمدﷺچالیس برس تک ایک گھپامیں گیان دھیان کرنے جاتے رہے۔ تیاگ ضروری تھا ورنہ
جو کچھ انہیں اُدھر ملا وہ گھر میں بھی مل سکتا تھا۔ تو کیا ثابت نہیں ہُوا کہ
اچھے کرم ، راست گوئی، نیک نیتی ، درست عقل اور کامل ارتکاز کے بغیر نجات ممکن
نہیں ۔ میرا ماننا ہے کہ ان سب کے کارن ہی دکھوں ، خامیوں اور بے ہود گیوں سے
مُکتی ملتی ہے اور انسان مارگ(راہِ نجات) تک پہنچتا ہے‘‘
مریم کوئی اور سوال کرنا چاہتی تھی کہ آمنہ نے ہاتھ کے اشارے سے
روکا اور خود گویا ہوئی: ’’گوتم سدھارتھ کے شاگرد آنند نے ان کی موت سے قبل کچھ
پوچھا تھا۔ جانتے ہیں کیا پوچھا تھا؟‘‘
’’نہیں ۔۔۔۔ کیا پوچھا تھا؟‘‘
’’پوچھا تھا کہ استاد کیا تم ہی آخری
ہو؟۔۔۔۔ گوتم کا جواب تھا کہ آخری وہ ہوگا جو کھجوروں والے ریگستان میں جنم لے گا۔
جانتے ہو یہ پریڈکِشن کسی ہستی کے متعلق تھی؟‘‘
بھکشو نے نفی میں سر کو جنبش دی۔
’’ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کے متعلق‘‘ بھکشو بھونچکارہ گیا۔
’’معاف کیجئے گا‘‘ آمنہ نے سلسلہ کلام
جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ’’آپ جس مکتی کے متلاشی ہیں ، اُس راہ پر نہیں ملے گی جس پر
گامزن ہیں ۔ آپ اپنی جستجو کا سفر معلوم اور کامل سچائی سے کیوں نہیں کرتے۔
سدھارتھ کا زمانہ گزر چکا۔ تب انسانیت بچپنے کے عہد میں تھی اور پھر گوتم کا تیاگ
محض حصولِ نروان کے لیے نہ تھا۔ بات کچھ اور تھی۔ معروضی بے اطمینانی کے خلاف
بغاوت تھی۔ آریائی جبریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک فرد کی منظم کوشش تھی۔ آپ
کی اپنی تاریخ ہے ۔ جانتے ہوں گے کہ برہمنیت جس نے آریائی جارحیت سے جنم لیا، اس
نے قدیم ہند کو چار طبقوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی حاکمیت برقرار رہ سکے۔ ہزاروں
برس تک اچھوت کم ذات ظلم کی چکی میں پستے رہے اور یہ بد نصیبی ہنوز بھی باقی ہے۔
برہمنی سخت گیری کی موجودگی میں آزادئ فکر اور جرأتِ اظہار کی ابتدا سدھارتھ اور
مہاویر کی وساطت سے ہوئی۔ آستک روایت کے برخلاف ناستک رواج نے جنم لیا۔ آغاز میں
یہ داخلی انفرادی ردِ عمل تھا، بعد میں عوامی مقبولیت ملی۔ مقصود ذات پات کی تقسیم
، ویدک دیو والا اور حکمران اشرافیہ کے مفاد پر ستانہ گورکھ دھندے کو مسترد کرنا
تھا۔ سدھارتھ کی یہ کاوش اپنے عہد کے لحاظ سے جدید اور روشن خیال بلکہ تغیر کی
حامی ، ذاتی ملکیت کی مخالف اور پرانے دیوتاؤں کے خاتمے کے حق میں تھی۔۔۔۔ مگر ایک
تضاد جو باقی رہ گیا ،یہ ہے کہ وہ قدیم تصورتناسخ سے مکتی حاصل نہ کر سکے جس کے
درد ناک چکر سے چھٹکارے کے لیے نروان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ وہ مارگ (راہِ
نجات) کو دائرہ سمجھنے پر مجبور رہے ۔اگر صراط مستقیم جانتے تو دکھوں سے آگے نکلنا
سہل ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا مظلوم شخص تھا کہ جس کے پیروکاروں نے اس کی اصل تعلیمات
کو بھلا کر اسے دیوتا بنا دیا اور اسی پرستش نے بُدھا کی حقیقی منشا کو جامداور بے
اثر کر کے رکھ دیا۔بر ہمینت کویہ دیکھ کر انتقام ک سُوجھی۔ موقع مناسب ملا تو اس
نے بدھ ازم کو از سرنَو ویدک روایت میں ضم کر لیا۔ یہ المیہ تمام مذاہب کو در پیش
رہا۔ آخر کار انسانیت اپنے دورِ بلوغت کو پہنچی۔ جدید اور کامل سچائی نے پچھلے
تمام قوانین اور تعلیمات کو معطل کر دیا۔ ۔۔۔ تو میرے محترم!۔۔۔ میں آپ کو دعوت
دیتی ہوں کہ بے شک آپ اپنا تیاگ جاری رکھیں مگر مناسب سمجھیں تو دینِ اسلام، اس کے
کامل ترین دستور اور مُعلّمِ عظیم حضرت محمد ﷺ کے لیے کچھ وقت مختص کر لیجئے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ قدیم غلام
گردشوں میں بھٹکنے کی بہ جائے جدید رہگزر آپ کی بہترین رہنمائی کرے گی ‘‘
بھکشو جو عالم مرعوبیت میں آمنہ کو سن رہا تھا ، اُس کی آنکھوں
میں چمک بھر گئی اور دلچسپی نے اس کے ہونٹ واکیے: ’’براہِ کرم بولتی رہیں ۔ یہ
کامل دستور سے آپ کی کیا مراد ہے ؟‘‘
’’میری مراد الہامی کتاب قرآن مجید سے
ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل کی۔ یہ کتاب تمام انسانیت کو غوروفکر کی دعوت اور مطالعۂ فطرت کی
ترغیت دیتی ہے۔ اعلیٰ ظرف اور کشادہ قلب لوگوں کے لیے اس میں واضح نشانیاں ہیں ۔
یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور چیلنج کرتی ہے کہ اس جیسی
ایک بھی آیت کوئی بنا کر دکھا دے۔ چودہ سو برس گزر گئے۔ دعویٰ اور دعوت برقرار ہیں ‘‘
’’کیا واقعی؟‘‘
’’جی ہاں۔۔۔ جنہیں اپنی ذہانت اور
علمیت پر بہت گھمنڈ تھا وہ زِچ ہو کے رہ گئے ۔ ایک بات کا جواب دیجئے۔ سچائی کا
حتمی معیار آپ کی نظر میں کیا ہے؟‘‘
’’جس کا متبادل کوئی نہ ہو‘‘ بھکشو نے
بے دھڑک کہا۔
’’بالکل درست کہا آپ نے ۔ قرآن کا بھی
کوئی متبادل نہیں ‘‘
’’اور وہ جو آپ نے معلّمِ عظیم کے
بارے کہا۔ ذرا مزید بتائیے‘‘ بھکشو نے بند مٹھیاں کھول اور دوبارہ بند کر تے ہوئے
کہا۔
’’قرآن حکیم کی عملی تصویر جس ہستی نے
پیش کی وہ معلّمِ عظیم حضرت محمد ﷺ ہی تو ہیں ۔ کیا آپ کو عمرانیات کے موضوع سے دلچسپی ہے؟‘‘
’’جی بالکل۔۔۔۔۔‘‘
پھر آپ جانتے ہوں گے کہ تہذیب کی ترقی میں علم کا کردار بے حد
اہم ہوتا ہے ۔ سابقہ تمام مذاہب اور تہذیبوں کی تاریخ کھنگال لیجئے۔ ہر بالادست
گروہ نے زیر دستوں پر علم اور حکمت کے دروازے نہ صرف بندکیے رکھے بلکہ کوئی ایسا
کرنے کا مرتکب ہُوا تو اسے بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ دُور کیوں جاتے ہیں ۔
سنسکرت جو علم و حکمت اور اسرار و رموز کی زبان تھی اور جس پر برہمن کا راج رہا،
اچھوتوں کے لیے اس کا سیکھنا ممنوع تھا۔ حتیٰ کہ کسی اچھوت کے کانوں میں غلطی سے
بھی پروہت کا الاپ پڑجاتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا جاتا تھا۔
یہ اسلام ہی ہے جس نے حصولِ علم کو عبادت اور ہر خاص و عام کے لیے لازم ٹھہرایا
تاکہ تو ہمات اور فضولیات سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ سب سے پہلے معلّمِ عظیم
نے خود عمل کر کے ثابت کیا کہ ہر عاقل و بالغ انسان الہام و خرد کی روشنی میں
صراطِ مستقیم پر گامزن رہ سکتاہے ۔ جسے آپ مارگ کہتے ہیں‘‘
’’محترم خاتون! پھر اتنے شاندار مذہب
میں فرقے کیوں پیدا ہو گئے۔ سنتا ہوں کہ ہر ایک خود کو مبنی برحق سمجھتا اور دوسرے
کو جھوٹا کہتا ہے اور جان لینے اور دینے سے بھی نہیں گھبراتا ۔ اس کی وجہ؟‘‘
’’ہاں ۔۔۔ یہ حقیققت ہے۔ ایسا ہُوا
اور ہورہا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب احکاماتِ الہیہ کو نظر انداز کر دیاگیا اور
غیر علمی فروعات کو حقائق پر ترجیح دی جانے لگی تو اختلافات کا آغاز ہوا۔ ان
خرابات سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ نقصان سراسر پیروکاروں کا ہی ہُوا۔ باہمی
مناقشوں نے داخلی توانائی سلب کر لی۔ شخصی تنگ نظری، فرقہ ورانہ قضیّوں ، نسلی
تعصبات اور سیاسی ہوسِ اقتدارنے فکری، سماجی اور معاشی توازن کو متاثر کیا۔ یہ نا
قدری کا شاخسانہ ہے۔ ‘‘
بھکشو ، آمنہ کی دانش سے مغلوب ہو چکا تھا۔ اسی اندازمیں پوچھا:
’’کیا آپ بھی کسی شعبۂ تدریس سے
وابستہ ہیں ؟‘‘
’’نہیں۔۔۔ میں صرف گرہستن ہوں‘‘
’’تعجب ہے۔ میں نے آج تک ایسی گرہستن
عورت نہیں دیکھی جو اتنے اِدق موضوع پر روانی سے بول سکتی ہو۔ آپ کا علم میرے سارے
علم سے زیادہ ہے۔ میں رائے قائم کرنے اور فیصلے تک پہنچنے میں ہمیشہ دیر کرتا آیا
ہوں۔ دیکھتا ہوں جس قدر وثوق سے آپ بول رہی تھیں اس پر اتنا ہی گہرا یقین بھی
رکھتی ہیں‘‘
’’یہ آپ کا حُسنِ ظن ہے تاہم میرا
خیال ہے کہ انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے ‘‘
’’بے شک۔۔۔۔!!!‘‘
اسی اثنا میں بس کے ہارن کی گونج سرائے کے گردوپیش میں پھیلنے
لگی ۔ مسافر بس کی طرف بڑھنے لگے تو ہم اٹھے۔ بھکشو بھی کھڑا ہو گیا۔
’’آپ کا اگلا پڑاؤ کہاں ہو گا؟‘‘ میں
نے پوچھا۔
’’ٹیکسلا جاؤں گا۔۔۔ اور سوات بھی‘‘
’’خدا کرے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں ۔ آپ
کو نئی منزلیں مبارک ہوں ‘‘۔
’’یقینا‘‘ بھکشو نے یہ کہتے ہوئے اپنے
گلے سے ایک مالا اتاری اور مریم کو پہناتے ہوئے آمنہ سے مخاطب ہُوا’’اور میں آپ کی
پیشکش پر مخلصانہ عمل کروں گا‘‘ جواباً آمنہ مسکرادی ۔ بھکشو نے وداعی تعظیم دی۔
میں نے پُر جوش مصافحہ کیا۔
جب تک ہم بس میں سوا رنہیں ہو گئے وہ نیک طینت انسان کھڑا رہا۔
بقیہ سفر میں اُس کی بے داغ مسکراہٹ ہماری ہم سفر رہی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(١٣)
۔۔۔باب
سیزدھم۔۔۔
خانم!
انسان کی بساط ہے ہی کیا۔ کائنات کی وسیع بے کرانی میں
ہم صرف دو قدموں کے رقبے تک محدود رہتے ہیں ۔ کہیں بھی چلے جائیں اس سے اضافی جگہ
ہمارے تصرف میں آہی نہیں سکتی حالاں کہ جیتے جی ہماری آرزو کُل جہاں کو اپنے
بازوؤں میں سمیٹ لینے کی ہوتی ہے مگر موت ہمیں اپنے ہی دو قدموں پر لِٹا دیتی ہے۔
ہم اپنے دیرینہ مستقر پر جا پہنچے تھے۔ گویا دم دار
ستاروں نے دائروی سفر کے بعد اپنے ابتدائی پڑاؤ کو جا لیاہو۔ وہاں ویرانیوں نے گھر
کر لیا تھا۔ ہر سُو مکڑی کے جالے ٹنگے تھے ۔ جھینگروں کی آوازیں تھیں ۔ خود رَو
جنگلی جھاڑ جھنکاڑ میں لکڑی سے بنا وہ دیدہ زیب دو منزلہ گھر تقریباً چھپ چکا تھا۔
حشرات الارض اور جنگلی جانوروں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے ۔ گھر سے ملحقہ وسیع علاقہ
آمنہ کے آباواجداد کی جاگیر تھا جو بھر پور زندگی گزار کے ایک چھوٹے سے سر سبز خطۂ
زمین میں محوِ خواب تھے۔ اس چھوٹے سے گورستان کی آخری آرام گاہوں پر شاعرانہ
عبارتوں والے کتبے نصب تھے جن سے خود رو پھول دار بیلیں لپٹ گئی تھیں اور لامبی
گھاس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ چہار اطراف کے باغات میں بیش تر پھل دار درخت سوکھ
چکے تھے ۔ انگوروں کی بیلیں مایوس اور ویران پڑی تھیں ۔ چشموں کے رواں پانی کے لیے
بنائی گئی نالیاں مٹی اور پتوں سے اٹی پڑی تھیں ۔ پانی روٹھ کر اپنی گزر گاہیں جدا
کر چکے تھے ۔ وقت کی بے نیازی خوب ہویدا تھی ۔ سارا ماحول بے آسرا یتیم کی مانند
دِکھتا تھا جو روتے روتے سو گیا ہو اور آنسوؤں کے نشان رخساروں پر رہ گئے ہوں ۔
کبھی وہ عنبریں ، مخملیں اور خواب آگیں سمن زار تھا مگر اب وہاں واہموں کے بسیرے
تھے۔
آمنہ نے جب پہلی نظر اس سارے منظر پر ڈالی تو بہت روئی ۔
دوزانوبیٹھ گئی ۔ بڑی دیر آہ و زاری کی۔ ہمیں بھی رنجیدہ کیا۔ جن رشتوں نے ہمیں
اپنی دہلیز سے الوداع کہا تھا، وہ منوں مٹی تلے جا سوئے تھے۔
دل کی جھیل تا دیر آنکھ کے کناروں سے باہر چھلکتی رہی۔
ہماری آمد کی خبر پھیلی تو پرانے ملازمین کی اولادیں لوٹ
آئیں ۔ اگلے کئی دن گھر کو صاف اور ازسرِنَو قابلِ رہائش بنانے میں گزرے ۔بے
سروسامانی تو تھی نہیں بے امانی کا احساس بھی دب گیا۔ یہاں مکانات کے فاصلے تھے
مگر مکینوں کے نہیں ۔ آمدورفت ہونے لگی۔ بہت سے ہاتھوں کی معاونت میسر آئی تو جلد
ہی اجاڑ ویرانہ پرانے چمنستان میں بدل گیا۔ چشمے نئے سرے سے آب جوؤں میں بہنے لگے۔
انگوروں کی بیلیں کونپلیں نکالنے لگیں ۔ پرندوں کی چہچہاٹ گونجنے لگی۔ سبزے کے
تختے خوشنما ہونے لگے ۔ قبروں کے کتبوں پر کندہ شاعرانہ عبارتیں واضح ہو گئیں ۔
گھر کی بالکونیوں میں مریم کے قہقہے بکھرنے لگے۔ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں کا ساتھ
مل چکا تھا۔ وہ اس نئے اور اجنبی چوکھٹے میں ہمیں خوش نظر آئی۔ آمنہ بھی قریب و
دُور سے آنے والی قرابت دار عورتوں میں گھری رہنے لگی ۔ اس کی متوازن ، فصاحت آمیز
اور مقامیت سے ہم آہنگ ہونے والی دانش بھری گفتگونے بہت جلد سب کو اپنا گرویدہ بنا
لیا۔ ممنونیت تو تھی ہی، مرعوبیت بھی چھا گئی۔ ان دونوں کے حُسنِ سیرت اور کردار
کے تذکرے نشیب و فراز تک پہنچنے لگے۔
وہ تھیں ہی ایسی کہ اگر شہر سے نکلتیں تو دشت و صحرا
آباد ہو جاتے۔
گھر کا ہر گوشہ پرانی اپنائیت سمیت جاگ اٹھا تھا۔
ایک دن، موسمِ خزاں کی اولین برسات میں مَیں اور آمنہ
گھر کے پچھواڑے جھجے دار زینے پر بیٹھے نشیبی جنگل میں بھٹکتے دُھندکے مرغولوں کو
دیکھ رہے تھے ۔ میں نے پوچھا:
’’اب تو خوش ہو ناں؟‘‘
اس نے دھیرج سے اپنا سر میرے شانے سے ٹکایا اور لگاوٹ سے
بولی! ’’ہاں ۔۔۔ آپ بہت اچھے ہو فہیم۔۔۔۔ بہت اچھے۔ وہ لمحہ بہت خوش نصیب تھا جب
آپ پہلی بار اس جنگل میں سے گزر کر یہاں تک پہنچے اور میں نے آپ کو دیکھا۔ اسی
زینے پر بیٹھی تھی۔ وہ دن میری کُل زندگی کے دنوں میں منفرد ہے۔ ۔۔۔ معلوم ہوا
جیسے آپ میرے لیے ہی پیدا ہوئے۔۔۔۔ گویا میں آسمانوں میں تھی اور بادلوں کے رتھ پر
سوار اور آپ؟ ۔۔۔۔۔ ہزارسازوں کی سمفنی لے کے پہنچے۔ ان بلندیوں سے نیچے دیکھتی
ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ آپ میرے بھیانک خوابوں کی دلکش تعبیر بن کے رُونما
ہوئے۔ ۔۔۔۔ یہاں سینے میں وہ آگ ابھی تک جل رہی ہے جو آپ نے اولین لمحے میں سلگائی
تھی۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔!‘‘
’’مگر کیا؟‘‘ میں نے لرزکے پوچھا۔
’’ایندھن ختم ہونے کو ہے ‘‘
’’ایسی باتیں نہ کرو آمنہ۔۔۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ۔ ہم
ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ۔ ہرے رہے تو ہرے رہے۔ سوکھیں گے تو ایک ساتھ ۔ فرقت کی
بات مت کرو‘‘
’’آپ نے مجھے محبت کرنے کا ڈھنگ سکھایا فہیم ۔ ۔۔۔ میں
نابلد تھی۔ جذبہ تھا پر سلیقہ نہ تھا میرے پاس۔ چاہنے اور چاہے جانے کی طلبگار تو
تھی البتہ طریقہ کون سا ہو۔۔۔ اس سے لا علم تھی۔ آپ کے انداز، وارفتگی، بے خودی،
عقیدت اور خانم سے سنگین نوعیت کی وابستگی نے میرے ہاتھ میں وہ نصاب تھما دیا جسے
حرزِ جاں بنا کے میں نے منزلیں طے کیں۔ آپ وہ وسیلہ ہو جس کے بغیر میرے قدم کبھی
اٹھ نہ سکتے۔ پر آپ کبھی خود پر منکشف نہ ہو سکے ۔ آپ کو اپنی قدر کرنی نہ
آئی۔۔۔۔۔ پارس ہو۔۔۔ جسے چھُو لیا اُسے کیا سے کیا بنا دیا‘‘
’’ہیں ۔۔۔ میں نے؟‘‘ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔
’’ہاں آپ نے
!‘‘
’’بات کو ٹالنا کوئی تم سے سیکھے۔ جو خود شہابِ ثاقب ہے
اور قرنوں سے بے کنار خلاؤں میں آوارہ پھرتا ہے اسے تم پارس کہہ رہی ہو۔ خوب مذاق
ہے بھئی‘‘ میں ہنس پڑا۔
حضرت رومی ؒ فرما گئے۔ عشق اول در دلِ محبوب پیدا
شُد(عشق پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتا ہے)۔ جس جذبے کی جوت جگائے پھرتے ہیں ۔۔۔
اس میں میں نے آج تک کوئی کمی نہیں دیکھی۔ یہ کس کی دین ہے؟۔۔۔ آپ مغرور، ہرلحظہ
ڈوب جانے کے خدشے میں مبتلا، شکوک وشبہات سے لبریز اور بیزار تھے۔۔۔ پھر یہ عجز،
یہ بے خوفی، یہ یقین اور یہ طلب کہاں سے آئی؟‘‘
(جواب تو آپ تھیں خانم۔ میں کیا کہتا۔ آمنہ خود واقف تھی)
آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔
’’روئیے مت فہیم۔۔۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے‘‘ روتی ہوئی آمنہ
نے اپنی بے قابو تمکنت سے کہا۔
’’بہتیرے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنا قفس ہمراہ لیے
پھرتے ہیں ۔ اپنے زنداں سے رہائی کس طور ملتی ہے ۔ میں نہیں جانتا ۔ میں تو جس طلب
کا قتیل ہوں اس سے بھی ہنوز آشنا نہیں ۔پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟‘‘
’’آپ ان میں سے ہیں جن کی تپش نگہ سے بستیاں بھسم ہوجاتی
ہیں اور جن کا نقش اگر ثبت ہو جائے تو موت کی لذت بھی سوا ہو جاتی ہے ۔ نسبت بڑی
چیز ہے فہیم ۔ ضروری نہیں کہ ہر متمنی کو اس کا مقام بتا دیا جائے۔ مراد اپنے
ضرورت مند کو جس طرح خود دریافت کرتی ہے اسی طرح فیض رساں بھی بنا دیتی ہے ‘‘ ۔
دفعتاً اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اوربولی:
’’میں برسوں سے یہ کرامت دیکھتی آرہی ہوں ‘‘
میں سراسیمہ اُسے دیکھتا گیا۔
’’آج یومِ وصیت ہے۔ وعدہ کیجئے۔ اپنی طلب کی شدت میں
کبھی کمی نہ آنے دیں گے ۔اس آگ کو کبھی مدہم نہ ہونے دیں گے۔ وعدہ کیجئے!‘‘
’’کیا میں اس لائق نہیں کہ تمہیں اپنے لیے زندہ رکھ سکوں
؟‘‘
’’کوئی بچھڑتا نہیں ہے فہیم۔۔۔ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے
درمیان ۔ ہاں حد سے زیادہ قیام کی مہلت سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ۔۔۔ یہ
بڑی سعادت کی بات ہے جنہیں وصیت چھوڑ دینے کی رعایت مل جائے‘‘
’’اپنے الفاظ واپس لو آمنہ۔۔۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے‘‘
میرے اندر کا بچہ مچل اٹھا۔
’’آج مجھے بولنے دیں ‘‘ اس کے چہرے پہ سارے بدن کا خون
سمٹ آیا اور آنکھوں کے سرخ ڈورے مزید سرخ ہو گئے اور جسم تھر تھرانے لگا۔ مجھے لگا
زمین سرک گئی ہو۔ ‘‘مریم کی رضا کا خیال رکھےئے گا۔ ۔۔ اسے اپنی زندگی جینے کا
اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ملا۔ وہ کسی کی امانت ہے ۔جب وقت آئے تو اسے سونپ دیجئے
گا۔ میں نے اپنی لحد کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ میری خاک کا خمیر یہیں سے
اٹھا تھا۔ اپنی ماں کے پہلومیں دفن ہونا چاہتی ہوں ۔ مجھے ماں کی آغوش نصیب نہیں
ہوئی ۔ مجھے جنم دے کر انہوں نے آنکھیں موند لیں تھیں ۔ سمیعہ خانم، جن کے خصائلِ
حسّنہ کے قصے میں اپنے والد ضرار احمد خان سے سنتی رہی۔ وہ شاعر، مصّور اور عمدہ
موسیقی کی شائق تھیں اور حضرتِ رومی ؒ کے دیس سے آئی تھیں ۔ اپنے محبوب شوہر کے
ساتھ ۔ میرے والد جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ متحدہ ہندوستان کی فوج میں
لفٹین تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اپنے بدیسی آقاؤں کا حکم ماننے سے اس لیے
انکار کر دیا کہ مقابل اپنے ہم مذہب تُرک تھے۔ خلاف ورزی کی سزا موت تھی اور وہ
فرار ہو گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔بَرِعظیم منقسم ہو گیا تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے
ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے ۔ ہمارا یہ چوبی آشیانہ میرے ماں کے خلاق ذہن کا شاہکار ہے
۔ میں اسی گھر میں اپنے والدین کی شادی کے بارہ برس بعد پیدا ہوئی ۔ اپنی عزیز اور
محبوب شریکِ حیات کی اکلوتی نشانی کی میرے والد نے بیس سال تک ہر خواہش اور ضد
پوری کی۔ ہتھیلی کا چھالہ بنائے رکھا۔ میں اپنی ماں کا ہُو بہُو عکس ہوں ۔ ۔۔۔ جن
دنوں آپ پہلی بار یہاں آئے تو میں ایک انوکھے جذبے کی آنچ پر پگھلنے لگی۔ اس کیفیت
کا اظہار میں نے مکمل صداقت سے اپنے والد کے رُو بہ رُو کیا۔ اُن کو بھی آپ بھا
گئے تھے ۔ مگر آپ اپنے آپ میں نہ تھے ۔ اور میرا یہ حال کہ جن دیواروں کو روز
دیکھتی تھی ۔ ۔۔ ان میں رنگ ہی رنگ بھر آئے ۔ بدن پر لگتا ہزاروں آنکھیں ابھر آئی
ہیں ۔ جس سمت دیکھتی ایک ہی میلہ نظر آتا۔ جذبے بدل گئے۔ عجیب عجیب سے خواب دیکھنے
لگی۔ آپ کا قیام لمحاتی تھا۔ کوئی فیصلہ صادر کےئے بغیر آپ پلٹ گئے اور میں نے آپ
کو عقب سے پکارا۔ آپ ٹھٹھک کے رکے اور میں نے وہ سب کچھ سنا ڈالا جو میں محسوس کر
سکتی تھی۔ آپ تو اس دن جنگل میں غروب ہو گئے خود میں نصف النہار پر جا ٹھہری ۔ پھر
ایک خواب دیکھا اور انہیں دیکھا جنہیں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا ہی جمال آفریں
صورت تھی۔ مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ بھینچا اور تادیر اپنی نگہ کے محیط میں رکھا۔
میری کایا کلپ ہو گئی۔ جاتے جاتے فرما گئیں:’’وہ پلٹ کے آئے گا جو ڈوبنے سے ڈرتا
ہے‘‘ ایسا ہی ہوا اور آپ آگئے۔ دور اس نشیبی خطے اور جنگل میں سے گزر کے جس میں آپ
برسوں پہلے غروب ہوگئے تھے۔ یہی جگہ تھی۔ اسی زینے پر بیٹھی تھی۔ ایسی ہی بارش
تھی۔ آج جیسا ہی موسم تھا۔۔۔ اور آپ اچانک ہی میرے مقابل آگئے تھے۔ وقت کتنی جلدی
بیت گیا فہیم‘‘
’’کاش ہم وقت سے بے نیاز ہُوا کرتے ‘‘ میں مسلسل رنج سے
مغلوب ہو کے بولا۔
آمنہ معّطر اگربتی کی طرح اپنے اختتامی سرے پر سلگ رہی
تھی۔ سرِمژگاں آنسوؤں کے دیپ ٹمٹماتے تھے۔ بھنور میں گھِرا ہوا انسان دائرے میں
گھومتا ہچکولے کھاتا ہے اور چشمِ اجل مسکراتی ہے ۔ گزرے ہوئے واقعات کی یادیں
دراصل شیشۂ ذہن پر کھینچی ہوئی خراشیں ہیں جو ماتھے کی جلد تلے چھپ کر تفکر ، تردد
اور غم کے تجریدی مرقعّے بن جاتی ہیں ۔ عمرِ رفتہ کے اوراق پلٹتی آمنہ کی پیشانی
پر کچھ ایسی ہی علامتی کہانی ابھر رہی تھی۔ وقت کا مغنی سوز کے دف پر تھاپ دیتا
گزررہا تھا اور چوبی زینے پر تھکے ہوئے دو رقاص بیٹھے تھے جن کی سانسیں حلق میں
معلق ہو گئی تھیں ۔
’’آقا حضور نبی کریم ﷺ نے ایک عربی شاعر لبید کے اس شعر کی بہت تعریف کی تھی ‘‘
الا کل شیئی ما خلا اللہ باطل
وکل نعیم لا محالۃ زائل
(خبر دار! ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ باطل نہیں
اور دنیا کی ہر قسم کی نعمت ختم ہونے والی ہے )
فہیم! بہت سی آرزوئیں کی تھیں اگر وہ درست ہوئیں تو اچھی
ہوں گی ورنہ ہم نے کافی زمانہ عیش و عشرت میں گزاردیا۔ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ
کے لیے محبت کی اور اس طریق پر چلنا میرے لیے سہل نہ تھا اگر خانم کی رہنمائی نصیب
نہ ہوتی اور آپ کا وفورِ عشق کا انداز میرے لیے مثال نہ ہوتا۔ آپ نے خانم کو ان کے
ظاہری جاہ وحشم کے ساتھ دیکھا ہوگا اور دل میں جانے کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے ہوں
گے۔ ان کی وجاہت اور حسن میں کوئی شک نہیں البتہ ان کی امارت سراسر مشاہدہ ہے اور
بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تامرگ مجاہدہ ہوتا ہے ۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ
وہ کسی کو شان و کروفّردے کے آزماتا ہے اور کسی کو خاک بسری دے کر۔ یہ دونوں راہ
کی منزلیں ہیں ۔ جو اللہ والے ہوں تو وہ مقامات سے فانی اور احوالِ ظاہری سے نجات
پائے ہوئے ہوتے ہیں ۔ حضرت اماں رابعہ بصری ؒ یوں ہی تو آگ اور پانی لے کر نہیں
نکل پڑی تھیں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور جہنم کو بجھا دیں تاکہ لوگ جنت کی لالچ اور
جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت نہ کریں ۔ بلکہ خالصتاً اس کی رضا کی خاطر عبادت
کریں۔ جو اللہ کی محبت کے گرویدہ ہوں ان میں کچھ تو اس کے انعامات واحسانات کے عوض
محبت کرتے ہیں اور بعض احسانات وانعامات کو اللہ کی دوستی کے غلبے کی بہ دولت حجاب
کا سبب جانتے ہوئے راہِ نعیم کو مقصود و مطلوب ٹھہراتے ہیں ۔ محبت عطائے ربانی ہے
۔ یہ نہ تکلف و اہتمام سے دل میں لائی جا سکتی اور نہ جبر سے نکالی جا سکتی ہے ۔
جناب داتا ہجویریؒ نے کیا خوب فرمایا کہ دل کی ترکیب اضطراب سے بنائی گئی ہے ۔ سو
سب سمندر دل کے سامنے سراب ہیں ۔ ہر وہ دل جو محبت سے خالی ہو بے کار اور مردہ ہے‘‘
آمنہ اس سمے وہ تان تھی جو بلند ہوئی اور اپنی اثر
آفرینی کو پھیلا کر واپس سَم پر آٹھہری تھی۔ اس کے سولہ ماترے میں نے ہمہ تن گوش
بن کر سنے۔ یہ راگ کیدارا نہایت میٹھا، مدھر، دل کو چھو لینے والا اور فرقت کو
ابھارنے والا تھا۔ پریم کی دھیمی آنچ پر وہ موم کی مانند پگھلتی آئی تھی۔ ۔۔۔ اب
شمع دان سے سوز کا دُھواں اُٹھ رہا تھا۔
بارش رُکی، دھوپ نکلی اور ڈھل بھی گئی۔ شام دبے پاؤں آئی
اور برقی چراغ روشن ہوگئے۔ ہم تشنہ اور ناآسودہ اُٹھے اور لرزتے جذبات کے ساتھ
سنگی روش پر چلتے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ بالائی منزل کی بالکونی میں بیٹھی
مریم آئندہ کے زمانوں میں کھوئی ہوئی دیکھی گئی۔ اس کی ریشمی شال کا پلو فاتح لشکر
کے پرچم کی طرح لہرا رہا تھا۔
-----------------------
(۱۴)
خانم!
پھر یوں ہوا کہ آمنہ ہم میں نہیں رہی ۔ عجیب بے مہر لمحہ
تھا جو ایک وجودی برہان کے ساتھ موت کا سندیسہ لایا اور آمنہ نے کمال تسلیم و رضا
کے ساتھ رختِ سفر باندھا اورمسکراتی ہوئی اجنبی منطقوں کے باحجاب موسموں میں چلی
گئی۔۔۔ اور پیچھے رہ گئے ہم باپ اور بیٹی ۔ پیچھے رہ جانے والوں کے پاس رہ ہی کیا
جاتا ہے۔ سوائے اشکوں کے جو صبح شام آمنہ کے تعویزِ مزار پر گرتے رہے، تحسینِ وفا
کی صورت۔ اپنی بے پایاں محبت کی نذر صرف اسی طور ہم دے سکتے تھے۔ ہمارے آنسوؤں کا
صحیح مسکن سینۂ زمیں ہی ہے کہ یہ نہ رخساروں پہ ٹھہرتے ہیں اور نہ پتھروں میں جذب
ہوتے ہیں ۔
وہ اپنی عزیز ماں کے پہلے میں جا سوئی، کسی معصوم شیر
خوار کی طرح جس میں تادیر جدائی کی تاب نہیں ہوتی۔
اس کی موت سے ہم نے جانا کہ دوامِ تمنا سراب ہے ۔ صرف
خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ۔ تب ایک الگ نم سے ہماری آنکھیں معمور رہنے لگیں ۔
تاریکیاں نور رہنے لگیں ۔
فرقت کا غم اتنا کڑا ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے لیے حرفوں
کی زنجیر بن نہیں پاتی ۔ قلم کے قدم راستہ چھوڑ دیتے ہیں ۔ میں آج تک آمنہ کے کہے
گئے لفظوں کی تعبیر ، لہجے کی تفہیم ، نگاہ کی تفسیر اور خوابوں کی تجسیم سے نہیں
نکل پایا۔ اپنی مرضی کی دُھن مجھ میں نہیں جاگی۔ اسی کی لگن کی لَے میرے بدن کے ساز
پر بجتی آئی تھی ۔ آپ نے خانم میری روح کو ساز بنا دیا اور آمنہ کی الفت کو دُھن
۔۔۔ جو گم ہو گئی اور سازابھی تک تھرتھرا رہا ہے۔ ہمارا ساتھ ادھورا رہ گیا۔۔۔ اور
ادھوری تصویر صدیوں کے مشاہدے سے بھی مکمل نہیں ہو سکتی ۔
تقدیر کا کہانی کاراور ہدایت کار کسی کردار کے مشورے اور
مرضی کا پابند نہیں ۔ جو اس نے لکھ دیا اور جوطے کر دیا، بس وہی ہوتا ہے ۔ زیست کی
تمثیل میں ہر کردار اپنے لکھے کا زندانی ہے ۔ اتنا ہی پیش کرتا ہے جتنا ہدایت کار
چاہے۔ جو ذرا بھی کھسکا تو اسے بلا یا جاتا ہے ۔ کڑی تنبیہ اور سرزنش کے ساتھ ۔
جینے کا ناٹک تو حقیقت میں مرنے سے بھی دشوار ہے ۔ ہم جو جیتے جی مر جاتے ہیں تو
ہدایت کار کہتا ہے : ’’کٹ! یہ کوئی مرناہے؟ نو ٹنکی کرتے ہو۔ ری ٹیک۔۔۔۔
کیمرہ۔۔۔۔۔ لائٹس آن! چلو پھر سے مرکے دکھاؤ۔ تاثرات حقیقی ہوں ۔ حرکات و سکنات
میں کوئی ریا کاری نہ ہو۔ اپنے مرے ہوؤں کا تصور کرو کہ وہ کہاں گئے۔ ذرا سوچو کہ
واقعی مر گئے ہو۔ اپنی نیت ٹھیک کرو کہ ہر عمل کا دارومدار اسی پر ہے ۔۔۔ لیکن
نہیں ! تم مرنا ہی نہیں چاہتے ۔ جیب اور پیٹ بھرا ہوتو فنا کا خیال کیسے آئے۔ اسی
لیے تمہاری اداکاری میں جان نہیں پڑ رہی۔ ۔۔۔ خاتمے کے بارے مت سوچو۔ کہانی میں نے
لکھی یا تم نے؟ چاہوں تو ایک دورانیے میں نپٹا دوں ، چاہے سلسلہ وار چلنے دوں ۔
تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم تھے ہی کیا؟ جو ہو تو کیا ہو؟ محض
کردار۔ جب چاہوں گا تمہیں مار دوں گا۔۔۔ ایک دن سارے کھیل کا پردہ بھی میں ہی گِراؤں
گا‘‘
آمنہ کا کردار ختم ہو گیا تھا۔ اسے وجودی موت دے دی گئی
تھی ۔
ہم ابھی تک ریہرسل میں مبتلا ہیں ۔کہانی جاری ہے ۔ سب
پردہ گرنے کے منتظر ہیں ۔
میں نے آمنہ کی موت کو تسلیم نہ کیا، تب تک کہ مجھے وہ
تجربہ نہ ہو گیا جب کوئی زمین پر چلتے چلتے اچانک پانی پر قدم رکھنے لگے تو بری
طرح کھٹک جائے اور سنبھلتے سنبھلتے بھی گرِ جائے۔ جینے اور مرنے میں خاک و آب جیسا
فرق ہے ۔ عجیب دلدلی سی سچائی ہے ۔
زیست ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی دم ساز سہارے کی محتاج ہوتی
آئی ہے ۔ اتنی عادی ہو جاتی ہے کہ قبر میں بھی اترے تو کندھے سے ہی اترتی ہے ۔
خنک بارچشموں سے کچھ دُور وسیع سبزہ زار جس میں اگر کچھ
نمایاں دِکھتا تو وہ سفید وسرمئی سنگِ مرمر کی بنی قبریں تھیں جن میں آمنہ کی قبر
باقیوں سے مانوس ہو چکی تھی ۔ یہاں چند صنوبر کے قدیمی پیڑ بھی تھے جن کی شاخیں
تجریدی مصوّری کی قوسوں کی مانند ابھرواں ، خمدار اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں
کی طرح تھیں جن پر ہر نوع کے پرندے نغمہ سنج تھے۔ اس افسانو ی نوعیت کے گورستان کے
مکینوں کا ذوق بھی کبھی یہی رہا تھا جو موسیقی ، مصوّری، علم، ادب اور دیگر جمیل
فنون کے رسیا تھے۔ قدرت کی وسیع الظرف فیاضی رُکی نہیں تھی۔ فیض رواں تھا۔
مجھے کافی تعطل کے بعد ایک مکتوب ملا۔ عبارت جانی پہچانی
تھی۔ میں نے اسے آمنہ کی لحد پربہ آوازِ بلند پڑھا:
’’سانحے اور صدمے گھر اور گور کو یکساں طور پر متاثر
کرتے ہیں مگر استقامت کو شکستہ پائی سزاوار نہیں ۔ قیام کی بہ جائے کوچ کے لیے ہر
لخطہ تیار رہو کہ یوں روح کوزنگ نہیں لگتا اور یہ آئینہ اندھا ہونے سے مامون رہتا
ہے ۔
یہ پیغام ہمارے الٹے سفر کا نشان تھا۔کسی اور دیس کی
جانب ہجرت کی حکم آپہنچا تھا۔مریم اس خوابِ زار میں اپنی محبوب ماں کی ابدی خواب
گاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ خط کی عبارت پڑھ چکا تو میں نے اس کے آنچل سے ڈھکے سر
پر دستِ شفقت رکھا اور کہا:
’’اُٹھو بیٹا! چلیں‘‘
اس نے مزار پر ملائمت سے ہاتھ پھیرے گویا صاحبۂ مزار کی
غیر مرئی زلفوں کو سنوارا ہو پھر قدرے خمیدگی کے ساتھ لوحِ مزار کو رم کر ایستادہ
ہوئی تو پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی ترکی باداموں جیسی آنکھوں میں اندوہ کا
رُکا ہوا سیلاب دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیلِ اشک بہہ نکلا ۔ ہچکیوں کے وقفے میں
ایک ہی لفظ ’ماں‘ کی تکرار تھی۔
اچانک کہیں سے بہت سی تتلیاں آگئیں اور آمنہ کی قبر پر
منڈلانے لگیں ۔
’’صبر۔۔۔ میری بچی ۔۔۔ صبر!‘‘ تجربہ نہ ہو تو دلاسا دینا
کتنا دشوار ہوتا ہے ۔ مجھے کوئی اسلوبِ تسلی معلوم نہ تھا۔ ناچار میں نے اپنی
لرزاں استقامت کو اپنی بیٹی کے شانے کے سپرد کر دیا ۔زندگی ہمیشہ سے سہارے کی
محتاج ہوتی آئی ہے ۔
(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)
(۱۵)
درختوں کے نیچے خزاں رسیدہ پتوں کا زرد سونا بکھر رہا تھا کہ حکیم
نشتر انصاری سفر کے ایک ایسے مرحلے میو ملے جب ہم نے اگلی منزل کے لیے گاڑی بدلنی
تھی۔
وہ جس والہانہ پن سے ملے اس نے بیتے دنوں کی یاد تازہ کر
دی ۔ ہمارے ساتھ آمنہ کو نہ پا کر ان کی شہرۂ آفاق ہنسی بھاپ بن کر اُڑ گئی۔ وہ سب
کچھ بھانپ گئے۔
’’اے ساکنِ وادئ دلدار! کچھ اُدھر کی سنائیے؟‘‘ میں نے
پوچھا۔
’’ارے میاں! کچھ نہ پوچھو۔ زلزلے کا مرکز کہیں بھی ہو
مگر اثر کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے ۔ بھائی نورو بھی چل بسے۔ محبوب کی کوئی خبر
نہیں ۔ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ماسٹر خوشحال سنگھ اپنے پوتے پوتیوں
کے ہاں تھائی لینڈ سدھار گئے۔ حافظ شمسی کی بینائی مکمل طور پر رخصت ہو گئی۔ موہن
داس کا کفر خدا خدا کر کے ٹوٹ گیا، عبدالرحمٰن بن گئے اور خدیجہ سے نکاح کر کے
دونوں سُوئے طیبہ روانہ ہو گئے۔ محرم کے بغیر ویزہ نہیں مل رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے
کہ موہن داس ، خدیجہ کے عشق میں مبتلا چلے آئے تھے ۔ قدرت بھی زبردست حکمت والی ہے
۔ ملایا بھی تو کیسے ۔ کیا نصیب پائے ہیں دونوں نے ۔ آپ نے اپنا گھر جوخدیجہ بہن
کو تحفتہً دیا تھا، وہ دارُالمطالعہ بنا دیا گیا۔ ۔۔۔ اسی لائق تھا۔۔۔ بہت پر سکون
جگہ پر ہے ناں۔ مائی خیراں اس کی منتظم ہے ۔ میں نے اپنا ذخیرۂ کتب اس کے لیے عطیہ
کر دیا۔ مزید کتابیں خوشحال سنگھ نے دیں ۔ کچھ منگوائیں بھی ۔ میں پچھلے کئی دنوں
سے چکر میں ہوں ۔ اور آپ لوگ؟‘‘
’’قصۂ غم طویل ہے‘‘ میں نے افسردہ طمانیت کے ساتھ کہا۔
حکیم انصاری کچھ دیر مجھے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہے پھر بڑی گھمبیر آواز میں
بولے :
’’کوئی وقت جاتا ہے کہ بزمِ ہستی اُجڑ جائے گی ۔ اپنی
ساری عمر ضد میں گزری ۔ اب تسلیم کی عادت پڑنے لگی ہے ۔ ضد اختیاری تھی تو تسلیم
سراسر توفیق ہے ۔ مجھے فلسفے نے گمراہ کیئے رکھا۔ احکاماتِ اور فرائضِ شریعت پر جب
سے دیانتدار انہ غوروفکر کرنا شروع کیا تو پتہ چلا، فلسفہ تو ان کے آگے پانی بھرتا
ہے۔ فلسفہ عشق کی تفسیر کبھی نہیں کر سکتا۔ نورو کی موت سے چند دن پہلے ان کی ناؤ
میں بیٹھا تو بڑی زور دار بحث ہوئی تھی ۔ اس دن وہ جلال میں آئے ہوئے تھے۔
ناخواندہ تھے۔ لیکن علم کے معاملے میں ان سے میں بُری طر ح مارکھا گیا۔ کہنے لگے
کہ کس دنیا میں رہتے ہو۔ خود تو گھاس کی ایک پتی ایک ذرۂخاک یا خلیۂ انسانی تک
بنانے پر قادر نہیں اور تصرف کرتے ہو قادرِ مطلق کے معاملات میں ۔ خدا کی شان ۔۔۔۔
بت مسلمان ہونے جا رہے ہیں تو یہ حضرت کافری پر بہ ضد ہیں ۔ ان دنوں موہن کی نورو
سے گاڑھی چھننے لگی تھی ۔بعد میں جلد ہی موہن نے ان کے ہاتھ پر بیعتِ دین کی اور
عبد الرحمٰن ہوئے ۔ ان کے دلائل نے میرا سینہ شق کر دیا اور میرے زعم کے چیتھڑے
اُڑادیئے۔ علمِ معرفت کے آثار کے پورے جانکار تھے ۔ میں نے لاجواب ہو کر سپر ڈال
دی تو بولے۔ مہلت جتنی بھی ملے اسے غنیمت جانو۔ ازالے کی نیتِ صادق بھی نجات کے
لیے کافی ہوتی ہے ۔ لہٰذا فہیم میاں ! چکر میں آیاہُوا ہوں ۔ حادثے اور خوشیاں
کبھی التوا میں نہیں رہتیں ۔ ہر وقوعہ اپنے متعینہ زمانی چوکھٹے میں تصویر ہو جاتا
ہے ۔ اسباب و علل اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں ۔ نتائج کو مانے بغیر جان نہیں
چھوٹتی۔ میں نے ساری عمر قیام کیا اب کوچ پرمامو ر کر دیا گیا ہوں ۔ کسی کا حکم ہے
کہ روح کو زنگ لگوانے سے بہتر ہے ، گردش میں رہو۔ پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی
گئی ہے تو میں بھی اسے بہ ہر طور نبھاہنا چاہتا ہوں ۔۔۔ لیکن آپ کہاں کا قصد کیے
ہوئے ہیں ؟‘‘
’’جہاں قسمت لے جائے‘‘
’’لگتا ہے بساط سمیٹی جا رہی ہے ؟‘‘
’’پیادوں کی مجال ہی کیا ‘‘
’’ٹھیک کہتے ہو میاں! نہ مجنوں رہے گا اور نہ ویرانہ‘‘
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(۱۶)
موسم کی پہلی برف باری کے بعد سارے ماحول کو برف کے کفن
نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لُنج مُنج درختوں کے پتے آنسو بن کر جھڑ چکے تھے۔
ریل گاڑی اجنبی خطے سے گزر رہی تھی ۔ سورج کی کرنیں برف
پر سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں ۔ بہت کچھ تیزی سے گزر چکا
تھا اور باقی گزر رہا تھا ۔ میرے کانوں میں کچھ عجیب سا شور سنائی دینے لگا حالاں
کہ گاڑی کے اندر مدہم ، خوابیدہ اور مخمور سی آوازیں تھیں جو ناگوار محسوس نہیں
ہوتیں ۔ وہ شور کچھ ماتمی سا تھا۔
مریم کھڑکی کے ہوا بند شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہی
تھی ۔ کچھ دیر پہلے تک ہم نے ساری رات باتوں میں گزار دی تھی اور دونوں ہی اپنے
اپنے لفظوں کے سکے خرچ کر چکے تھے۔
میں نے آنکھیں بند کیں تو کسی اور جہان میں جا کھلیں
۔حلاوتوں ، لطافتوں اور راحتوں سے نوبت مفارقتوں ، صعوبتوں اور تلخ صداقتوں تک
پہنچی تو میں نے سہولت سے پاؤں پسار لیے۔ وہ لمحۂ حال کے مرگ زار سے لمحاتی گریز
تھا۔ یادوں کے معمر چیتھڑے حُزن کی تند ہواؤں میں پھڑ پھڑانے لگے تھے ۔
برباد زمانوں کے ملبے سے تازہ جہانوں کی تشکیل ہوتی رہے
گی۔ برف پگھلی تو زمین نئے سبز پیرہن سے ڈھک جائے گی ۔ سفر اجسام کا ہو یا نظریات
کا جاری رہے گا۔
ریل برف پوش ساحلوں کوچھُو کر بہت بڑا قوس بناتی ہوئی
گزر رہی تھی اور پیچھے ننگی پٹڑی دھوپ میں چمک رہی تھی جیسے کوئی جسیم خمدار تلوار
پڑی ہو۔ بہت دُور سمندر میں سست برفاب موجوں کی جھاگ ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی
پانی میں ضم ہو تی تھی۔ حدِ اُفق تک پھیلا وہ دورنگی منظر نگاہ کی ترائی میں اتر
گیا۔
پھر چلتی ہوئی ٹرین کے دونوں اطراف پہاڑیاں نمایاں ہو
گئیں جو کہیں کہیں بغل گیر ہوتیں تو سرنگ کی تاریکی اور سناٹے کو تیزی سے کاٹتی
ہوئی ریل کی آواز گھونسے کی مانند دل پر لگتی اور ایک دبنگ احساس کو جگا دیتی ۔
ہر منظر ہمارا میزبان تھا ۔
ہر راستہ ہماری رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔
سفر کو ہم درپیش تھے ۔
منزل ہماری منتظر تھی ۔
اور جب دھواں دیتی برف بھری آبادیوں سے گزرتے ہوئے ایک
درمیانے درجے کے پہاڑی ریلوے سٹیشن پر گاڑی رکی تو ہم زادِ سفر سمیت اتر گئے ۔ ہر
مقام سے پہلے دل و دماغ کسی انجانی قوت کے زیر اثر آجاتے تھے ۔ کہیں بھی ٹھہرنے
میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔
وہاں جو مسافر اترے وہ جلد ہی اگلی منزلوں کی طرف چلے
گئے ۔ سٹیشن پُر رونق نہیں تھا ۔ ویران اور سنسان بھی نہ تھا۔ مریم کو بھوک لگ رہی
تھی ۔ کھلے اور طویل پلیٹ فارم کی ایک چوبی شکستہ بنچ پر میں نے مختصر سامانِ سفر
رکھا اور مریم کو بٹھا کر خود قریب ہی ایک ٹھیلے والے سے پنیر ، سلاد، پیزا اور
پانی کی دو بوتلیں خریدیں اور واپس بنچ پر آبیٹھا۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی کھانا کھا
رہے تھے تو مخالف سمت سے ریل کے انجن کی سیٹی سنائی دینے لگی ۔ اسی اثناء میں ایک
شور سا پھیل گیا۔ اگلے چند لمحوں میں سرخ پھندنوں والی ٹوپیاں پہنے بہت سے لوگ ایک
بے حد خوبصورت سنہری تابوت کو کندھوں پر اٹھائے آگئے۔ تابوت کو نہایت احترام اور
احتیاط کے ساتھ ایک بڑی سی میز پر رکھ دیا گیا۔ لوگ متواتر بڑھتے چلے آرہے تھے اور
تابوت کے گرد دائرہ پھیلتا چلا جا رہا تھا ۔ میں اپنے منہ کے نوالے کو حلق سے نیچے
اتار نا بھول گیا اور دائرے کی طرف بڑھا ۔ ریل گاڑی بھی آپہنچی تھی۔ میں نے بھیڑ
کو چیر کر تابوت تک پہنچنے کی کوشش کی اور آخر کامیاب ہو ہی گیا مگر یہ جاننا ابھی
باقی تھا کہ میت ہے کس کی ۔ مرد ہے یا عورت؟
ایک شخص سر جھکائے تازہ گلابوں کی چادر کو تابوت پر سجا
رہا تھا ۔ پھول اور اقسام کے بھی بہت سے تھے ۔ دفعتاً اس شخص نے سر اٹھا، ایڑیوں
کے بل کھڑے ہو کر کسی کو نام لے کے پکارا تو مجھے اپنے وطن کے ایک شہر کی فٹ پاتھ
’ایک پھیلا ہوا ہاتھ‘ چند ناقابلِ فراموش الفاظ اور برسوں پرانی شام یاد آگئی۔
میرے پاؤں شل ہو گئے اور دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
ریل گاڑی ادھر جا رہی تھی جدھر سے ہم آئے تھے۔
میں نے سرجھٹک کر خود کو فعال رکھنے کی ناکام کوشش کی ۔
اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کئے بغیر میں نے تابوت
پر سجی پھولوں کی چادر ذرا سی کھسکائی اور اپنے واہمے کا بطلان کرنے کی سعی میں
شفاف شیشے میں سے میت کا چہر ہ دیکھنے کو اپنی نظر اندر پھینک دی مگر جتنی تیزی سے
نظر اندر گئی ، پلٹ کر اتنی ہی سرعت سے آنکھ میں آٹھہری۔ ناچار پلکوں اور ہونٹوں
کا متحدہ بوسہ تابوت پر ثبت کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔
اس بھیڑ میں رؤساء، شرفا اور مقتدر طبقے کے دیگر افراد
کے علاوہ افتادگانِ سماج کی کثیر تعداد شامل تھی۔ ہر چہرہ ملول، رنجیدہ اور سنجیدہ
تھا۔ سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہُوا تھا۔
تابوت دوبارہ کاندھوں پر اٹھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے
گاڑی کے روشن کارگو کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا گیا۔ انجن کی وسل گونجی، بھیڑ چھٹنے لگی
۔ حتیٰ کہ جہاں تابوت رکھا ہوا تھا، اب اس جگہ صرف میں ہی کھڑا رہ گیا۔ ریل چل پڑی
تھی۔ وقتِ عصر ڈھل رہا تھا ۔ موسم کے تیور بدلنے لگے تھے ۔
مڑتے ہوئے نظر دفعتاً پلیٹ فارم کے فرش پر گرے ہوئے ایک
غنچۂ گلاب پر پڑی جسے میں نے اٹھا لیا اور مٹھی میں دبائے نڈھال قدموں کے ساتھ
مریم کی طرف بڑھا جو بنچ کے قریب کھڑی ریل گاڑی کے ہیولے کو دیکھے جاتی تھی ۔
’’لو بیٹا! ۔۔۔ اسے سنبھال کے رکھنا‘‘۔ میں نے غنچۂ گلاب
اسے تھماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ غنچے کی مہک سے جانے کیسے حقیقت پا گئی۔ بولی:
’’بابا! خانم بھی ہمیں چھوڑ گئیں ؟‘‘ اور بے پناہ بے چارگی کے ساتھ روتی ہوئی بنچ
پر گر گئی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔ختم
شد۔۔۔
واہ کینٹ
09نومبر2012ء
-------------------
دیدبان شمارہ ۔۷
ناول پس غبار سفر
مصنف خالد قیوم تنولی
آخری قسط
(١١ )
!خانم
ٹھیک تین دن بعد ہم نے گھر کی چابیاں خدیجہ کے حوالے کر دیں۔ یہ
تجویز بھی مریم کی تھی۔ بہ قول اس کے خدیجہ کو ہمارے گھر کا محلِ وقوع بہت بھاتا
تھا کیوں کہ اس کی مماثلت اسے اپنے اطالیہ کے آبائی علاقے، گھر اور بالپن کی یاد
دلاتی تھی۔ وہ طرب زار یاد آفرینی کی پریشان تتلی ایک بوئے گرفتار تھی مگر یہ جان
کر کہ زیست کے باقی ماندہ ایام سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے کے لیے ہم اس کے حضور
میں وہ نذر گزر رہے ہیں جو اسے مرغوب تھی تو وہ سیراب روح ہمارے بے حد اصرار کے
بعد رضا مند ہوئی اور ہم نے اس کی پیرانہ آنکھوں کو دیکھ کر جانا کہ ویران مزاروں
پر جلتے ہوئے چراغ کیوں اتنے بھلے لگتے ہیں ۔ روشنی زندگی کا استعارہ ہے۔ زندگی
احساس ، شوق اور درد بھی ہے۔ جو کچھ بھی تھا نہ ہمارا اور نہ ہی مستقل خدیجہ کا
رہنے والا تھا۔ لافانی تو وہ جذبہ تھا جو تھوڑی دیر کے لیے سہی اسکی روح میں وسعت
بھر رہا تھا اور اس کی عمر رسیدہ مسکراہٹ کو اداس سی شوخی دے رہا تھا اور اس کے
جذباتِ تشکر سے کپکپاتے لہجے کو مسرت سے نواز رہا تھا۔
رخصت ہونے سے قبل آمنہ نے اسے ایک چھوٹی سے پوٹلی بھی تھما دی۔
’’یہ کیا ہے؟‘‘
’’آپ کے خواب کی تعبیر‘‘
’’کیسی تعبیر؟‘‘
’’آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منّورہ کی
زیارت کی متمنی جو ہیں ‘‘
’’مگر اس کے لیے تو پس انداز کر رہی
ہوں ۔ یہ میں نہیں لوں گی‘‘
’’میں کون سا اپنے پاس سے دے رہی ہوں۔
یہ تو امانت ہے جو آپ تک پہنچانا میرا فریضہ تھا‘‘
’’سبحان اللہ ۔ جس نے حاضری کی التجا
قبول کی وہی اسبابِ سفر بھی عطا کر رہا ہے‘‘۔
’’بے شک خدیجہ جی۔۔۔ اور اس سے بھی
بڑھ کر وہ تسکینِ قلب ہے جو آسائشِ ہستی کی دلیل ہے‘‘
’’ہاں ۔۔۔ ہاں۔۔۔۔ اصل سرمایہ تو یہی
ہے۔ دل کی امیری کا اب خوب اندازہ ہُوا‘‘
’’جب آپ وہاں حاضر ہوں تو ہمارے لیے
رحمت اور بخشش کی دعا کرنا نہ بھولیئے گا‘‘
’’’’ضرور۔۔۔ ضرور۔۔۔۔‘‘ خدیجہ رونے
لگیں اور روتے روتے انہوں نے اپنی بانہیں واکیں ۔ اتنی واکیں کہ ہم تینوں ان کی
وسیع اور اعلیٰ ظرف آغوش میں سمٹ گئے۔ ان کی ہچکیاں بلند ہو گئیں ۔ پتہ نہیں کب
مائی خیراں بھی آگئیں اور اپنی پیوندزدہ اوڑھنی کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھنے
لگیں ۔
ان نم دیدہ ساعتوں میں دونوں بزرگ خواتین سے ہم نے اذنِ رخصت لیا
اور اپنے عقب میں آباد بستی کی رونقوں کو چھوڑ کر ندی کی جانب اترتے راستے پر ہو
لیے۔
کھیتوں میں دہقان مرد اور عورتیں کا م میں مصروف تھیں اور سورج
ان کے سروں کے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت سے ہاتھ پیشانیوں تک اٹھے اور وداعی انداز
میں لہرائے۔ جواباً ہم نے بھی یہی کیا۔ اس ادا میں دوستی ،بے تکلفی، دلبری، خلوص
اور اپنائیت کے رنگ تھے اور ہمارے دل و دماغ پر ان ہی رنگ بہ رنگ جلوؤں کا جمگھٹ
تھا۔ کچھ دیر کی اس دیدنی چاہت نے پر چھائیں ہو جانا تھا۔
چلتے چلتے ہم ندی کے اس پاٹ پر جا کھڑے ہوئے جہاں ہماری عمروں
کے کثیر لمحے بیتے تھے۔ سولہ برس کی مدت ایک دم سے نظروں میں گھوم گئی۔ سفر آگے کا
ہو یا پیچھے کا کوئی نہ کوئی دریا حائل ہو ہی جاتا ہے مگر نشانِ سوال ہو یا رکاوٹ
تا دیر حائل نہیں رہتی۔ صرف احتسابِ یاد در پیش ہوتا ہے۔ تہذیبوں کے میلے ہوں یا
یادوں کے جھمیلے، کنارِ آب ان کی رونق کئی چند ہو جاتی ہے ۔
نورو ملاح کی ناؤ ندی کے اس پار سے واپس پلٹ رہی تھی ۔ گمبھیر
ترنم میں گنگناتے بوڑھے ملاح کی دبنگ لَے ہم تک پہنچ رہی تھی:
’’عیشِ منزل ہے غریباںِ محبت پہ حرام
’’سب مسافر ہیں بہ ظاہر نظرآتے ہیں
مقیم‘‘
ناؤ دھیرے دھیرے کنارے تک پہنچی تو میں نے مضمحل شائستگی سے
کہا: ’’اے ساکنِ وادئ دلدار ہم چلے۔۔۔۔۔‘‘ نورو ایک با وقار اور دل گرفتہ ہنسی
ہنسا اور پتوار چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے سر تھام ، ہمیں اپنی نگہہ کے محیط میں لا
کر بولا:’’ تو پھر یہ طے ہے کہ تم لوگ جا رہے ہو؟‘‘
’’ہاں بابا!‘‘
’’واپس آؤ گے؟‘‘
’’خدا بہتر جانتا ہے‘‘
’’سجنو! میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ بانکا
سجیلا۔ فوج کا سپاہی۔ محاذ پر گیا۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو آنکھ
سے باہر کبھی نہیں جھانکتے۔ میں نے واپسی کی امید اس کے تیوروں میں کھودی۔ کوئی
مہینہ بھر بعد جنگ تھم گئی۔ ڈاک کا ہر کارہ آیا اور تار دے گیا کہ جس کا ذکر تمہیں
ہر شے سے پیارا تھا وہ دشمن کی زمین پر دشمنوں کے نرغے میں کام آگیا ہے۔ جس کا مال
تھا اس نے واپس لے لیا۔ اللہ کی مرضی برحق مگر جو یہ دل ہے، یہ تو روتا ہے۔ سو میں
بھی رویا۔ بہت دنوں تک روتا رہا۔ اس کی ماں بھی روتی رہی مگر باہمت عورت تھی۔ ایک
دن میرے جھکے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی: ’’مت رو نُورو۔
آنکھیں بے نور ہو جائیں گی ۔ میں کہاں سے تیرے لیے قمیضِ یوسف لاؤں گی۔ مت رو
نورو‘‘۔ میں نے آنسو پونچھے۔ پتوار سنبھالے۔ ناؤ میں آبیٹھا۔ آؤ بیٹھو مسافرو۔۔۔۔!‘‘
ہم ایک دل گیرا حساس سمیت نورو کی الم نصیب فراست سے لاجواب ہو
کر ناؤ میں سوار ہوئے۔ اس نے چپو تھامے اور ناؤ کا رخ پھیرنے لگا۔ ناؤ نے چکر کاٹا
اور ایک لمحاتی ساگر داب بنا کر متعینہ جانب آگے بڑھنے لگی۔
’’زندگی اور موت کا فلسفہ میں نے ان
ہی دو کناروں کے درمیان سے سیکھا ہے فہیم!‘‘ نورو نے سلسلۂ کلام جوڑتے ہوئے کہا:
’’کبھی نہیں ملتے یہ دونوں ۔ مل جاتے تو روانی نے کب باقی رہنا تھا۔ درمیان میں
وقت بہتا ہے۔ سارے بھنور، تلاطم ، ہمواری اور سکون وقت کے تابع ہیں ۔ انسان تو صرف
چپو چلاتا ہے۔ وجود کی کشتی کو متحرک رکھنے کے لیے ۔ اتنا ہی اختیار حاصل ہے ہمیں۔
درمیان میں رہ کر وقت کے ساتھ بہتے رہنا ہی مقدر ہے۔ کناروں سے باہر نکلنے کا
فیصلہ کسی اور کے پاس ہے۔ حکیم انصاری کو اتنی سامنے کی بات بھی دکھائی نہیں دیتی
۔ کملا کہیں کا۔ اور تم لوگ جا رہے ہو ایں؟۔۔۔۔ غالباً تیسری یا چوتھی مجلس تھی۔
مریم تُونے بیٹاایک نغمہ سنایا تھا۔ یاد ہے ناں؟۔۔۔ ہوجائے پھر آخری بار۔۔۔۔ سنا
دو میری سوہنی سجنی!‘‘
’’جی باباجی۔۔۔ سناتی ہوں ‘‘
’’اوئے زندہ باد ۔۔۔ بسم اللہ ۔۔۔ بسم
اللہ‘‘
مریم نے ایک بار ہمیں جھینپ کر دیکھا اور ہمارے تائیدی انداز سے
مطمئن ہو کر آنکھیں موندلیں اور ننھی منی لہروں کے سنگ اس کی مدھر آواز کا جادو
بھی بہنے لگا:
’’یہ جلوؤں کی تابانیوں کا تسلسل
یہ ذوقِ نظر کا دوام اللہ اللہ ‘‘
اور خانم ! میں آپ کو سوچنے لگا ۔ ان گنت صدیوں پر پھیلے ہجر کی
دھندچھُٹنے لگی اور دُور افق پر آپ کی وجود کی شبیہ طلوع ہونے لگی۔ مدتوں پہلے کا
دیکھا ہوا آپ کا شفیق سراپا مثلِ آفتاب میرے سامنے تھا۔ رنگوں ، خوشبوؤں ، خوابوں
اور لفظوں کی حد سے آگے تک ہمہ گیر ہوتا محسوس ہوا۔ لگا جیسے لپک کر آپ کے قدم چھو
لوں گا۔ سچ کہا تھا کسی کہنے والے نے کہ بعض بیج جو ایک بار خون اور گوشت میں اپنا
اکھوا ابھارنے میں کامیاب ہو جائیں تو چاہے کیسے ہی طوفان آئیں اسے جڑ سے نہیں
اکھاڑ سکتے۔ بانسوں کے جنگل کی طرح جڑوں کی شریانیں بکھیردیتے ہیں ۔ روح میں گھل
مل جاتے ہیں ۔
’’وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم
وہ آبِ رواں بے خرام اللہ اللہ‘‘
مریم کی آوازاثر پزیری کے ساحل سے جاملی اور ناؤ کنارے سے ۔ میں
نے کچھ روپے بابا نورو کو دینے چاہے تو اس نے نفی میں سر ہلایا: ’’افسوس تُوہر بار
بھول جاتا ہے فہیم۔ کرایہ میں کسی سے بھی نہیں لیتا۔ کبھی نہیں لیا۔ یہ تو کسی کا
حکم ہے جس کی بجا آوری کا وعدہ تادمِ مرگ نبھاتا رہوں گا۔ رزق کا وعدہ بھی پورا
ہوتا آرہا ہے۔ رکھ ان پیسوں کو اپنے پاس۔ تیرے کام آئیں گے‘‘ یہ کہہ کر اس نے
پتوار چھوڑے، اٹھا اور مجھے گلے سے لگالیا۔ آمنہ کے سر پہ دستِ شفقت پھیرا اور
مریم کی پیشانی کے بہت سے بوسے لیے۔ دعائیں دینے لگا۔
آمنہ بولی: ’’فاصلے، مرحلے اور راہوں کی جدائی بے معنی ہوتی ہے
بابا۔ ہمارے دل ملے ہیں تو اوجھل ہونے کا صدمہ بے حیثیت ہے۔ کلفتِ حیات ہیچ اور
آشوبِ غمِ مرگ ایک سائے کی مانند ہے۔ سدا کب ایک سے لیل ونہار رہتے ہیں ۔ ۔۔ جس
طرح اس بہتے پانی کی ایک یقینی منزل ہے بالکل ویسے ہی مسافت کی بھی۔ سفر سہانا ہو
یا کٹھن تمنا یہ ہو کہ جو منزل ملے وہ نجات آفریں ہو۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا‘‘
’’خدا حافظ میری بچی۔۔۔ خدا حافظ!‘‘
’’خدا حافظ بابا۔۔۔۔‘‘
ہم تینوں سر کنڈوں کے جھنڈوں میں سے گزرنے لگے اور اس جنگل کے
قریب ہونے لگے جس کے بھیدوں کی اوٹ سے بانسری کی لَے سنائی دیا کرتی تھی۔
کئی سچ ایسے ہوتے ہیں خانم! جنھیں سمجھنے کے لیے دریا عبور کرنا
پڑتا ہے۔ جو سکون کی کیفیت میں صدیوں سجھائی نہیں دیتے وہی جدائی کے وقت اپنی تمام
قوت اور سنگینی کے ساتھ ابھر آتے ہیں ۔ فاصلوں ، مرحلوں اور راستوں کی علا حدگی،
قرار اور جمود میں کبھی نہیں کھلتی لیکن فیصلے کی ندی کے پار عیاں ہوتی ہے۔ کہتے
ہیں سدہارتھ جیون کا میلہ چھوڑ کر گیان کی کھوج میں نکل گیا۔ برسوں گزار دیئے۔
واپس آیا تو بیوی نے پوچھا: ’’جو اتنے برسوں میں سیکھا کیا گھر میں ممکن نہ تھا؟‘‘
سدہارتھ جواب میں بڑے اسرار بھرے انداز میں مسکرایا: ’’ممکن تو
تھا مگر سمجھ میں کبھی نہ آسکتا۔ جوگ ضروری تھا‘‘
بعض تجربات عامیوں اور خواص کے یکساں ہوتے ہیں ۔ خوشی کے ساتھ
دردوسوز کی تخلیق بھی جب تک خود نہ کی جائے تو یہ آپوں آپ کبھی نہیں ملتے ۔ جوگ
بنا روگ کی لذت کسی دکان سے مول نہیں ملتی۔
چلتے چلتے میں نے تو اپنے آپ سے کہا تھا کہ خدا جانے نورو بھی
کس راز سے بھرا ہوا آدمی ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی: ’’مسافر ہے اپنے سفر کی دھن میں
کھویا ہوا۔ نہ اس دنیا پر قانع اور نہ ہی اخروی نجات کے لیے فکر مند۔ ایسے لوگ
سراسررضا ہوتے ہیں ۔ خالصتاً قدرت کے لیے مختص۔۔۔۔ انہیں ایک ہی بار آزمائش کی
بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا جاتا ہے۔ ساری بے قراری، اذیت، پشیمانی، خوف، ملال،
بھوک، مرض، کیف اور مسرت کا ذائقہ چکھ کر ان کا من شانت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اپنے
بھی نہیں رہتے۔ اسی کے ہو جاتے ہیں جو جس کا ہو جائے تو کسی اور کا نہیں ہونے دیتا‘‘
ہم جنگل کی شروعات میں چلے جا رہے تھے۔ خنکی گہری ہو رہی تھی۔
پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں میں سے گزرتی ہوا کی بہ دولت پتوں کی تالیوں کی
دھیمی دھیمی آواز تھی۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ فضا کی خوشگواری اور من کی بے کلی کے
امتزاج سے بہ خوبی آگاہ ہم تینوں ترچھی راہ پر اوپر ہی اوپر گامزن رہے۔ حتیٰ کہ وہ
مقام آیا جہاں میں نے ایک کُبڑے دریوزہ گر اور نوخیز دوشیزہ کو محوِ گفتگو دیکھا
تھا۔ دریوزہ گر کی کوئی خبر نہ تھی مگر نوخیز دوشیزہ میرے پیچھے خراماں خراماں چلی
آرہی میری بیٹی تھی۔ بھیدوں بھری ، پُر عزم اور بہ یک وقت نگاہ و قیاس کو
جھٹلادیئے جانے والے تصور پر قادر۔ میری دل کی تہہ سے سوال اٹھا ۔ میں نے چاہا کہ
اس سے پوچھوں ۔ کُبڑا دریوزہ گر کہاں گیا؟ مگر اس کی بے پناہ چُپ اور آمنہ کی وضاحت
کے سبب میں باز رہا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(١٢)
واپسی کا سفر بڑا طویل مگر زادِ راہ ناگزیر ، مختصر اور ہلکا
ہونے کی بہ دولت بڑی سہولت سے کٹتا رہا۔ بہت سے نظارے ہدفِ نظر رہے۔ چھُوٹے ہوئے
مقام کا احساس مسافروں کو ہر گام پر اداس کرتا رہا۔ اپنائیت کے حلقے سے باہر نکل
جانے اور مسلسل دور ہوتے چلے جانے کے خیال نے دل کو متواتر جکڑے رکھا۔ ہماری ہجرت
سائبیریائی مہاجر پرندوں جیسی تو نہ تھی کہ پلٹ کے جانے کے بہلاوے سے خود کو مطمئن
رکھ پاتے۔ پیڑطائروں کی مفارقت سے سوکھ نہیں جاتے۔ چند شائقین کے چلے جانے سے میلہ
اُجڑ نہیں جاتا۔
متحر ک زندگی دیرینہ بام ودر کو پھرسے دیکھنے کے لیے لوٹ رہی
تھی۔ عجیب کیفیت سی طاری ہونے لگی۔ میں بچہ بن گیا۔ بھولے بسرے فسوّں خیز واقعات
تحت الّشعورسے خود کو دہرانے کی غرض سے چشمِ وا کے سامنے آنے لگے ۔ بیتی ہوئی
زندگی کے ان ٹکڑوں کو دیکھنا عذاب نہ لگا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ انہیں روکنا محال تھا۔
مریم اس دوران اپنے مشاہدات مجھ سے بانٹ رہی تھی لیکن میں وہاں ہوتا تو اسے جواب
دیتا۔ وہ نہیں جان پائی کہ میں یادآفرینی کے بلیک ہول سے گزر رہا ہوں جس میں وقت
بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ دورانیہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور میں اپنے حال میں لوٹ
آیا۔
ہماری بس دریا کنار کے کی سیاہ تارکول والی سڑک پر رواں تھی۔ ہر
منظر لپک کر آتا اور کھلی آنکھوں کے رستے دل و دماغ میں اتر جاتا۔
میدانی وسعتیں جن میں خود روگھاس لہراتی تھی۔ بے ثمر اشجار بازو
اٹھائے کھڑے تھے۔ بے ترتیب مکانات اور افتادگانِ خاک کی متنوع صورتیں تھیں ۔۔۔ بس
کبھی کبھی پُر ہجوم آبادیوں میں سے گزرتی تو بھرے بازار اور ان سے ملتی آنتوں جیسی
پُر پیچ گلیاں دکھائی دیتیں ۔ اسبابِ زیست سے بھری دکانوں کے چھجے ، باغات،
میناروں سے گونجتی دعوتِ فلاح کی صدائیں ، مختلف زبانوں کی موسیقی، کہیں دھوپ اور
کہیں گھنے بادل ، بارش ، کوہستانی سلسلے پر پھیلے وسیع و عریض جنگلات، ماہر چھاتہ
برداروں کی مانند زمین پر اُترتے شام کے دھندلکے ، کروڑوں ستاروں کی متحدہ لَو سے
بھی نہ ٹلنے والی تاریکئ شب ۔۔۔ خیمۂ فلک کے نیچے سُبک رَو ہوائیں، پہاڑی نالے اور
ہماری بس متحرک تھی۔۔۔۔ اور میرا خیال بھی جو نا معلوم منطقوں سے ہوتا ہوا آپ تک
جا پہنچا ۔ مگر آپ کہاں تھیں ؟ ۔۔۔۔ آپ کو تصور کرتے ہوئے نا گاہ نظر اس بند
دروازے پر ٹھہر گئی جس پر عبارت درج تھی۔
’مکان فروخت ہو چکا ہے‘‘
میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آمنہ اونگھ رہی تھی ۔ اس کی لامبی سیاہ
پلکیں چینی پگوڈے کے چھجے کی مانند بند آنکھوں پر پڑی تھیں ۔ میں نے اس کے اندازِ
بے خبری کو بے حد اپنائیت سے دیکھا ۔ اس عروسِ دل کے گداز گالوں پر گردِ سفر کے
آثار تھے۔ میں دید کے اس بار کو تا دیر نہ اٹھا سکا کیوں کہ بس طعامِ شب کے واسطے
کسی سرائے کے باہر رک چکی تھی۔ تمام مسافر اتر گئے۔ یہ کوئی پرانے طرز تعمیر کی
حامل عمارت جس میں پتھر اور لکڑی کا بے دریغ استعمال ہُوا تھا۔ بدھ مندروں جیسی پر
اسرار اور پُر امن ۔ ہم یخ بستہ پانی سے ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہوئے ۔ ایک عمر
رسیدہ ملاز م نے احاطۂ سرائے کے ایک الگ تھلگ اور پر سکون گوشے تک ہماری رہنمائی
کی جہاں نہایت خوبصورت منقش لکڑی کی میز اور کرسیاں بچھی تھیں ۔ گیروے رنگ میں
ملبوس ایک بدھ بھکشو پہلے سے براجمان اپنے سفید چینی مٹی کے نقش و نگار والے
چاولوں سے بھرے پیالے سے شغل کر رہا تھا۔ داڑھی، مونچھیں ،بھنویں اور سر کے بالوں
سے قطعی آزاد۔ پاؤں میں چمڑے کے ہلکے اور سادہ چپل اور گلے میں خوش رنگ مالائیں ۔
اس کی لمبی مخروطی انگلیاں بے حد شائستگی اور نفاست سے نوالوں کو پیالے سے منہ تک
پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہی تھیں ۔ ہم تینوں بیٹھ چکے تو اس نے بڑی صلح جُواور بے
داغ مسکراہٹ سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ جواباً ہم بھی خوش خلقی سے مسکرائے ۔ ہمارے
قدموں کے نیچے دریائی گول سنگریزے بچھے تھے۔ آس پاس کے ماحول میں نمی ، خوشگوار
خنکی اور دھیمی دھیمی دھند سی چھائی تھی۔ آرام دہ نشستوں نے سفر کی تکان کو بہلا
پھسلا کر جانے کہاں بھیج دیااور ہم سہولت محسوس کرنے لگے تھے ۔ تھوڑی دیر بعد
ہمارا کھانا میز پر چُن دیا گیا۔ یہ اُبلی ہوئی سبزیوں ، یخنی، دلیے، چپاتی، چٹنی،
سلاد اور تازہ پھلوں کے عرق پر مشتمل تھا۔ کھانے کی شروعات میں بھکشو کو بھی دعوت
دی گئی جسے اس نے متشکر انہ انداز سے ٹال دیا۔ تاروں کی چھاؤں ، ہوا کے لطیف
جھونکوں اور تاریکی کی لپٹوں میں اس سفری طعام نے خوب لذت دی۔
مریم ، بھکشو کو دلچسپی سے دیکھے جا رہی تھی۔ دفعتاً بولی:
’’کیا مزے کی آزاد زندگی جی رہا ہے یہ آدمی۔ ہے نا بابا؟‘‘
’’ہاں بیٹا‘‘ میں نے کن اکھیوں سے
بھکشو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ’’زندگی ضرورت کی طرح گزارنی چاہیے۔ خواہش کی طرح
نہیں ۔ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں
ہوتی‘‘َ
آمنہ نے کہا : ’’آرزو سے بے نیازی، وقت کی المناکیوں سے باہر لے
جاتی ہے۔ غیر ضروری تقاضوں سے جی فرار چاہتا ہے اور جسم کے خس و خاشاک ساتھ چھوڑ
دیتے ہیں ‘‘
ہم سمجھے کہ وہ بھکشو ہماری گفتگو کو سمجھنے سے قاصر ہو گا مگر
وہ مسکرایا، دھیرے سے کھنکارا اور بولا: ’’آپ کی باتوں میں مخل ہونے کی جسارت پر
معافی چاہتا ہوں‘‘
ہم اکھٹے ہنس پڑے اور اسے خوش آمدید کہا۔
بھکشو بولا: ’’میں آپ سے متفق ہوں ۔ چند برس ہوئے یونیورسٹی کی
پروفیسری کو خیر آباد کہے ہوئے۔ من اُکتا گیا تھا مصنوعی زندگی جیتے جیتے ۔ جب سے
دنیا کو چھوڑا ہے جی بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تیاگ کا سفر مزید کتنی دیر جاری رہے۔
نہیں جانتا ۔ بس ہمہ وقت حرکت میں ہوں ۔ قرطاسِ جہاں طویل تر ہے اور لگتا ہے ابھی
تمہید بھی ختم نہیں ہوئی ‘‘
’’تیاگ کی مقصدیت کیا ہے؟‘‘ میں نے
پوچھا۔
’’تلاشِ حق‘‘
’’اپنے بارے کچھ مزید بتائیے‘‘
’’نسلاً تبتی ہوں ۔ پیدائش بھارت میں
ہوئی۔ تعلیم کا عرصہ اور جوانی نیپال میں گزری جب کہ ملازمت چین میں کی۔ پیکنک
یونیورسٹی میں ہندی زبان پڑھاتا رہا۔ مجھے آپ کوئی بھی نام دے لیں ۔ اب عام اور گم
نام رہنے پر اکتفا کر چکا ہوں ۔ مکتی پانے کے لیے مشہور و معروف ہونا ضروری تو
نہیں ناں۔۔۔۔ شہرت کی مدرا میں مست رہ کر کچھ بھی نہیں ملا۔ جُز کی اوقات ہی کیا
ہوتی ہے۔ اب کُل میں جذب ہونے کے سوم رس سے عیش کرنے کی ٹھانی ہے۔ آسائشات کی ہوس
بڑی راکھشس ہوتی ہے جناب۔ یہ بھید بڑی دیر بعد بُدھی میں سمایا ہے ۔ خیر یہ وقت
طلب باتیں ہیں ۔ کچھ دیر کا ساتھ ہے۔ کہیں آپ کو بیزار نہ کر دوں ۔۔۔۔‘‘
’’نہیں نہیں ۔ ایسا مت سوچیں ۔ آپ
ہمیں اچھے لگے ہیں ‘‘
’’شکریہ۔۔۔ اور آپ بھی تو بتائیے اپنے
متعلق‘‘
’’میں فہیم ہوں ۔ یہ آمنہ ہیں ، میری
جیون شریک اور وہ ہماری بیٹی ہے، مریم
‘‘
’’بھکشو نے دونوں کو تین بار سر جھکا
کر تعظیم دی اور اپنی بے داغ اور نستعلیق مسکراہٹ سے خوش وقت کیا۔
’’کیا تیاگ ضروری ہے؟؟‘‘ مریم پوچھے
بغیر نہ رہ سکی۔
’’یقیناًضروری ہے‘‘ بھکشو نے اپنی
مسکراہٹ کو طول دیتے ہوئے کہا۔ ’’جب من بے کل ہو توجانتی ہو کیا ہوتا ہے ؟ اچھا یہ
بتاؤ جب بے تابی ہو تو انسان اپنا مقام کیوں بدلتا ہے۔ یعنی کمرہ چھوڑ کر باہر
کیوں آجاتا ہے ۔ جواب کے لیے تیاگ ضروری ہے ۔ قرار کے لیے لازمی ہے ۔ عظیم بُدھانے
تیاگ کے کارن ہی نروان پایا اور تتھاگت بنے۔ آپ لوگ مسلمان ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ
آپ کے پیغمبر حضرت محمدﷺچالیس برس تک ایک گھپامیں گیان دھیان کرنے جاتے رہے۔ تیاگ ضروری تھا ورنہ
جو کچھ انہیں اُدھر ملا وہ گھر میں بھی مل سکتا تھا۔ تو کیا ثابت نہیں ہُوا کہ
اچھے کرم ، راست گوئی، نیک نیتی ، درست عقل اور کامل ارتکاز کے بغیر نجات ممکن
نہیں ۔ میرا ماننا ہے کہ ان سب کے کارن ہی دکھوں ، خامیوں اور بے ہود گیوں سے
مُکتی ملتی ہے اور انسان مارگ(راہِ نجات) تک پہنچتا ہے‘‘
مریم کوئی اور سوال کرنا چاہتی تھی کہ آمنہ نے ہاتھ کے اشارے سے
روکا اور خود گویا ہوئی: ’’گوتم سدھارتھ کے شاگرد آنند نے ان کی موت سے قبل کچھ
پوچھا تھا۔ جانتے ہیں کیا پوچھا تھا؟‘‘
’’نہیں ۔۔۔۔ کیا پوچھا تھا؟‘‘
’’پوچھا تھا کہ استاد کیا تم ہی آخری
ہو؟۔۔۔۔ گوتم کا جواب تھا کہ آخری وہ ہوگا جو کھجوروں والے ریگستان میں جنم لے گا۔
جانتے ہو یہ پریڈکِشن کسی ہستی کے متعلق تھی؟‘‘
بھکشو نے نفی میں سر کو جنبش دی۔
’’ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کے متعلق‘‘ بھکشو بھونچکارہ گیا۔
’’معاف کیجئے گا‘‘ آمنہ نے سلسلہ کلام
جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ’’آپ جس مکتی کے متلاشی ہیں ، اُس راہ پر نہیں ملے گی جس پر
گامزن ہیں ۔ آپ اپنی جستجو کا سفر معلوم اور کامل سچائی سے کیوں نہیں کرتے۔
سدھارتھ کا زمانہ گزر چکا۔ تب انسانیت بچپنے کے عہد میں تھی اور پھر گوتم کا تیاگ
محض حصولِ نروان کے لیے نہ تھا۔ بات کچھ اور تھی۔ معروضی بے اطمینانی کے خلاف
بغاوت تھی۔ آریائی جبریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک فرد کی منظم کوشش تھی۔ آپ
کی اپنی تاریخ ہے ۔ جانتے ہوں گے کہ برہمنیت جس نے آریائی جارحیت سے جنم لیا، اس
نے قدیم ہند کو چار طبقوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی حاکمیت برقرار رہ سکے۔ ہزاروں
برس تک اچھوت کم ذات ظلم کی چکی میں پستے رہے اور یہ بد نصیبی ہنوز بھی باقی ہے۔
برہمنی سخت گیری کی موجودگی میں آزادئ فکر اور جرأتِ اظہار کی ابتدا سدھارتھ اور
مہاویر کی وساطت سے ہوئی۔ آستک روایت کے برخلاف ناستک رواج نے جنم لیا۔ آغاز میں
یہ داخلی انفرادی ردِ عمل تھا، بعد میں عوامی مقبولیت ملی۔ مقصود ذات پات کی تقسیم
، ویدک دیو والا اور حکمران اشرافیہ کے مفاد پر ستانہ گورکھ دھندے کو مسترد کرنا
تھا۔ سدھارتھ کی یہ کاوش اپنے عہد کے لحاظ سے جدید اور روشن خیال بلکہ تغیر کی
حامی ، ذاتی ملکیت کی مخالف اور پرانے دیوتاؤں کے خاتمے کے حق میں تھی۔۔۔۔ مگر ایک
تضاد جو باقی رہ گیا ،یہ ہے کہ وہ قدیم تصورتناسخ سے مکتی حاصل نہ کر سکے جس کے
درد ناک چکر سے چھٹکارے کے لیے نروان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ وہ مارگ (راہِ
نجات) کو دائرہ سمجھنے پر مجبور رہے ۔اگر صراط مستقیم جانتے تو دکھوں سے آگے نکلنا
سہل ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا مظلوم شخص تھا کہ جس کے پیروکاروں نے اس کی اصل تعلیمات
کو بھلا کر اسے دیوتا بنا دیا اور اسی پرستش نے بُدھا کی حقیقی منشا کو جامداور بے
اثر کر کے رکھ دیا۔بر ہمینت کویہ دیکھ کر انتقام ک سُوجھی۔ موقع مناسب ملا تو اس
نے بدھ ازم کو از سرنَو ویدک روایت میں ضم کر لیا۔ یہ المیہ تمام مذاہب کو در پیش
رہا۔ آخر کار انسانیت اپنے دورِ بلوغت کو پہنچی۔ جدید اور کامل سچائی نے پچھلے
تمام قوانین اور تعلیمات کو معطل کر دیا۔ ۔۔۔ تو میرے محترم!۔۔۔ میں آپ کو دعوت
دیتی ہوں کہ بے شک آپ اپنا تیاگ جاری رکھیں مگر مناسب سمجھیں تو دینِ اسلام، اس کے
کامل ترین دستور اور مُعلّمِ عظیم حضرت محمد ﷺ کے لیے کچھ وقت مختص کر لیجئے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ قدیم غلام
گردشوں میں بھٹکنے کی بہ جائے جدید رہگزر آپ کی بہترین رہنمائی کرے گی ‘‘
بھکشو جو عالم مرعوبیت میں آمنہ کو سن رہا تھا ، اُس کی آنکھوں
میں چمک بھر گئی اور دلچسپی نے اس کے ہونٹ واکیے: ’’براہِ کرم بولتی رہیں ۔ یہ
کامل دستور سے آپ کی کیا مراد ہے ؟‘‘
’’میری مراد الہامی کتاب قرآن مجید سے
ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل کی۔ یہ کتاب تمام انسانیت کو غوروفکر کی دعوت اور مطالعۂ فطرت کی
ترغیت دیتی ہے۔ اعلیٰ ظرف اور کشادہ قلب لوگوں کے لیے اس میں واضح نشانیاں ہیں ۔
یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور چیلنج کرتی ہے کہ اس جیسی
ایک بھی آیت کوئی بنا کر دکھا دے۔ چودہ سو برس گزر گئے۔ دعویٰ اور دعوت برقرار ہیں ‘‘
’’کیا واقعی؟‘‘
’’جی ہاں۔۔۔ جنہیں اپنی ذہانت اور
علمیت پر بہت گھمنڈ تھا وہ زِچ ہو کے رہ گئے ۔ ایک بات کا جواب دیجئے۔ سچائی کا
حتمی معیار آپ کی نظر میں کیا ہے؟‘‘
’’جس کا متبادل کوئی نہ ہو‘‘ بھکشو نے
بے دھڑک کہا۔
’’بالکل درست کہا آپ نے ۔ قرآن کا بھی
کوئی متبادل نہیں ‘‘
’’اور وہ جو آپ نے معلّمِ عظیم کے
بارے کہا۔ ذرا مزید بتائیے‘‘ بھکشو نے بند مٹھیاں کھول اور دوبارہ بند کر تے ہوئے
کہا۔
’’قرآن حکیم کی عملی تصویر جس ہستی نے
پیش کی وہ معلّمِ عظیم حضرت محمد ﷺ ہی تو ہیں ۔ کیا آپ کو عمرانیات کے موضوع سے دلچسپی ہے؟‘‘
’’جی بالکل۔۔۔۔۔‘‘
پھر آپ جانتے ہوں گے کہ تہذیب کی ترقی میں علم کا کردار بے حد
اہم ہوتا ہے ۔ سابقہ تمام مذاہب اور تہذیبوں کی تاریخ کھنگال لیجئے۔ ہر بالادست
گروہ نے زیر دستوں پر علم اور حکمت کے دروازے نہ صرف بندکیے رکھے بلکہ کوئی ایسا
کرنے کا مرتکب ہُوا تو اسے بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ دُور کیوں جاتے ہیں ۔
سنسکرت جو علم و حکمت اور اسرار و رموز کی زبان تھی اور جس پر برہمن کا راج رہا،
اچھوتوں کے لیے اس کا سیکھنا ممنوع تھا۔ حتیٰ کہ کسی اچھوت کے کانوں میں غلطی سے
بھی پروہت کا الاپ پڑجاتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا جاتا تھا۔
یہ اسلام ہی ہے جس نے حصولِ علم کو عبادت اور ہر خاص و عام کے لیے لازم ٹھہرایا
تاکہ تو ہمات اور فضولیات سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ سب سے پہلے معلّمِ عظیم
نے خود عمل کر کے ثابت کیا کہ ہر عاقل و بالغ انسان الہام و خرد کی روشنی میں
صراطِ مستقیم پر گامزن رہ سکتاہے ۔ جسے آپ مارگ کہتے ہیں‘‘
’’محترم خاتون! پھر اتنے شاندار مذہب
میں فرقے کیوں پیدا ہو گئے۔ سنتا ہوں کہ ہر ایک خود کو مبنی برحق سمجھتا اور دوسرے
کو جھوٹا کہتا ہے اور جان لینے اور دینے سے بھی نہیں گھبراتا ۔ اس کی وجہ؟‘‘
’’ہاں ۔۔۔ یہ حقیققت ہے۔ ایسا ہُوا
اور ہورہا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب احکاماتِ الہیہ کو نظر انداز کر دیاگیا اور
غیر علمی فروعات کو حقائق پر ترجیح دی جانے لگی تو اختلافات کا آغاز ہوا۔ ان
خرابات سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ نقصان سراسر پیروکاروں کا ہی ہُوا۔ باہمی
مناقشوں نے داخلی توانائی سلب کر لی۔ شخصی تنگ نظری، فرقہ ورانہ قضیّوں ، نسلی
تعصبات اور سیاسی ہوسِ اقتدارنے فکری، سماجی اور معاشی توازن کو متاثر کیا۔ یہ نا
قدری کا شاخسانہ ہے۔ ‘‘
بھکشو ، آمنہ کی دانش سے مغلوب ہو چکا تھا۔ اسی اندازمیں پوچھا:
’’کیا آپ بھی کسی شعبۂ تدریس سے
وابستہ ہیں ؟‘‘
’’نہیں۔۔۔ میں صرف گرہستن ہوں‘‘
’’تعجب ہے۔ میں نے آج تک ایسی گرہستن
عورت نہیں دیکھی جو اتنے اِدق موضوع پر روانی سے بول سکتی ہو۔ آپ کا علم میرے سارے
علم سے زیادہ ہے۔ میں رائے قائم کرنے اور فیصلے تک پہنچنے میں ہمیشہ دیر کرتا آیا
ہوں۔ دیکھتا ہوں جس قدر وثوق سے آپ بول رہی تھیں اس پر اتنا ہی گہرا یقین بھی
رکھتی ہیں‘‘
’’یہ آپ کا حُسنِ ظن ہے تاہم میرا
خیال ہے کہ انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے ‘‘
’’بے شک۔۔۔۔!!!‘‘
اسی اثنا میں بس کے ہارن کی گونج سرائے کے گردوپیش میں پھیلنے
لگی ۔ مسافر بس کی طرف بڑھنے لگے تو ہم اٹھے۔ بھکشو بھی کھڑا ہو گیا۔
’’آپ کا اگلا پڑاؤ کہاں ہو گا؟‘‘ میں
نے پوچھا۔
’’ٹیکسلا جاؤں گا۔۔۔ اور سوات بھی‘‘
’’خدا کرے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں ۔ آپ
کو نئی منزلیں مبارک ہوں ‘‘۔
’’یقینا‘‘ بھکشو نے یہ کہتے ہوئے اپنے
گلے سے ایک مالا اتاری اور مریم کو پہناتے ہوئے آمنہ سے مخاطب ہُوا’’اور میں آپ کی
پیشکش پر مخلصانہ عمل کروں گا‘‘ جواباً آمنہ مسکرادی ۔ بھکشو نے وداعی تعظیم دی۔
میں نے پُر جوش مصافحہ کیا۔
جب تک ہم بس میں سوا رنہیں ہو گئے وہ نیک طینت انسان کھڑا رہا۔
بقیہ سفر میں اُس کی بے داغ مسکراہٹ ہماری ہم سفر رہی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(١٣)
۔۔۔باب
سیزدھم۔۔۔
خانم!
انسان کی بساط ہے ہی کیا۔ کائنات کی وسیع بے کرانی میں
ہم صرف دو قدموں کے رقبے تک محدود رہتے ہیں ۔ کہیں بھی چلے جائیں اس سے اضافی جگہ
ہمارے تصرف میں آہی نہیں سکتی حالاں کہ جیتے جی ہماری آرزو کُل جہاں کو اپنے
بازوؤں میں سمیٹ لینے کی ہوتی ہے مگر موت ہمیں اپنے ہی دو قدموں پر لِٹا دیتی ہے۔
ہم اپنے دیرینہ مستقر پر جا پہنچے تھے۔ گویا دم دار
ستاروں نے دائروی سفر کے بعد اپنے ابتدائی پڑاؤ کو جا لیاہو۔ وہاں ویرانیوں نے گھر
کر لیا تھا۔ ہر سُو مکڑی کے جالے ٹنگے تھے ۔ جھینگروں کی آوازیں تھیں ۔ خود رَو
جنگلی جھاڑ جھنکاڑ میں لکڑی سے بنا وہ دیدہ زیب دو منزلہ گھر تقریباً چھپ چکا تھا۔
حشرات الارض اور جنگلی جانوروں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے ۔ گھر سے ملحقہ وسیع علاقہ
آمنہ کے آباواجداد کی جاگیر تھا جو بھر پور زندگی گزار کے ایک چھوٹے سے سر سبز خطۂ
زمین میں محوِ خواب تھے۔ اس چھوٹے سے گورستان کی آخری آرام گاہوں پر شاعرانہ
عبارتوں والے کتبے نصب تھے جن سے خود رو پھول دار بیلیں لپٹ گئی تھیں اور لامبی
گھاس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ چہار اطراف کے باغات میں بیش تر پھل دار درخت سوکھ
چکے تھے ۔ انگوروں کی بیلیں مایوس اور ویران پڑی تھیں ۔ چشموں کے رواں پانی کے لیے
بنائی گئی نالیاں مٹی اور پتوں سے اٹی پڑی تھیں ۔ پانی روٹھ کر اپنی گزر گاہیں جدا
کر چکے تھے ۔ وقت کی بے نیازی خوب ہویدا تھی ۔ سارا ماحول بے آسرا یتیم کی مانند
دِکھتا تھا جو روتے روتے سو گیا ہو اور آنسوؤں کے نشان رخساروں پر رہ گئے ہوں ۔
کبھی وہ عنبریں ، مخملیں اور خواب آگیں سمن زار تھا مگر اب وہاں واہموں کے بسیرے
تھے۔
آمنہ نے جب پہلی نظر اس سارے منظر پر ڈالی تو بہت روئی ۔
دوزانوبیٹھ گئی ۔ بڑی دیر آہ و زاری کی۔ ہمیں بھی رنجیدہ کیا۔ جن رشتوں نے ہمیں
اپنی دہلیز سے الوداع کہا تھا، وہ منوں مٹی تلے جا سوئے تھے۔
دل کی جھیل تا دیر آنکھ کے کناروں سے باہر چھلکتی رہی۔
ہماری آمد کی خبر پھیلی تو پرانے ملازمین کی اولادیں لوٹ
آئیں ۔ اگلے کئی دن گھر کو صاف اور ازسرِنَو قابلِ رہائش بنانے میں گزرے ۔بے
سروسامانی تو تھی نہیں بے امانی کا احساس بھی دب گیا۔ یہاں مکانات کے فاصلے تھے
مگر مکینوں کے نہیں ۔ آمدورفت ہونے لگی۔ بہت سے ہاتھوں کی معاونت میسر آئی تو جلد
ہی اجاڑ ویرانہ پرانے چمنستان میں بدل گیا۔ چشمے نئے سرے سے آب جوؤں میں بہنے لگے۔
انگوروں کی بیلیں کونپلیں نکالنے لگیں ۔ پرندوں کی چہچہاٹ گونجنے لگی۔ سبزے کے
تختے خوشنما ہونے لگے ۔ قبروں کے کتبوں پر کندہ شاعرانہ عبارتیں واضح ہو گئیں ۔
گھر کی بالکونیوں میں مریم کے قہقہے بکھرنے لگے۔ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں کا ساتھ
مل چکا تھا۔ وہ اس نئے اور اجنبی چوکھٹے میں ہمیں خوش نظر آئی۔ آمنہ بھی قریب و
دُور سے آنے والی قرابت دار عورتوں میں گھری رہنے لگی ۔ اس کی متوازن ، فصاحت آمیز
اور مقامیت سے ہم آہنگ ہونے والی دانش بھری گفتگونے بہت جلد سب کو اپنا گرویدہ بنا
لیا۔ ممنونیت تو تھی ہی، مرعوبیت بھی چھا گئی۔ ان دونوں کے حُسنِ سیرت اور کردار
کے تذکرے نشیب و فراز تک پہنچنے لگے۔
وہ تھیں ہی ایسی کہ اگر شہر سے نکلتیں تو دشت و صحرا
آباد ہو جاتے۔
گھر کا ہر گوشہ پرانی اپنائیت سمیت جاگ اٹھا تھا۔
ایک دن، موسمِ خزاں کی اولین برسات میں مَیں اور آمنہ
گھر کے پچھواڑے جھجے دار زینے پر بیٹھے نشیبی جنگل میں بھٹکتے دُھندکے مرغولوں کو
دیکھ رہے تھے ۔ میں نے پوچھا:
’’اب تو خوش ہو ناں؟‘‘
اس نے دھیرج سے اپنا سر میرے شانے سے ٹکایا اور لگاوٹ سے
بولی! ’’ہاں ۔۔۔ آپ بہت اچھے ہو فہیم۔۔۔۔ بہت اچھے۔ وہ لمحہ بہت خوش نصیب تھا جب
آپ پہلی بار اس جنگل میں سے گزر کر یہاں تک پہنچے اور میں نے آپ کو دیکھا۔ اسی
زینے پر بیٹھی تھی۔ وہ دن میری کُل زندگی کے دنوں میں منفرد ہے۔ ۔۔۔ معلوم ہوا
جیسے آپ میرے لیے ہی پیدا ہوئے۔۔۔۔ گویا میں آسمانوں میں تھی اور بادلوں کے رتھ پر
سوار اور آپ؟ ۔۔۔۔۔ ہزارسازوں کی سمفنی لے کے پہنچے۔ ان بلندیوں سے نیچے دیکھتی
ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے ۔ آپ میرے بھیانک خوابوں کی دلکش تعبیر بن کے رُونما
ہوئے۔ ۔۔۔۔ یہاں سینے میں وہ آگ ابھی تک جل رہی ہے جو آپ نے اولین لمحے میں سلگائی
تھی۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔!‘‘
’’مگر کیا؟‘‘ میں نے لرزکے پوچھا۔
’’ایندھن ختم ہونے کو ہے ‘‘
’’ایسی باتیں نہ کرو آمنہ۔۔۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ۔ ہم
ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ۔ ہرے رہے تو ہرے رہے۔ سوکھیں گے تو ایک ساتھ ۔ فرقت کی
بات مت کرو‘‘
’’آپ نے مجھے محبت کرنے کا ڈھنگ سکھایا فہیم ۔ ۔۔۔ میں
نابلد تھی۔ جذبہ تھا پر سلیقہ نہ تھا میرے پاس۔ چاہنے اور چاہے جانے کی طلبگار تو
تھی البتہ طریقہ کون سا ہو۔۔۔ اس سے لا علم تھی۔ آپ کے انداز، وارفتگی، بے خودی،
عقیدت اور خانم سے سنگین نوعیت کی وابستگی نے میرے ہاتھ میں وہ نصاب تھما دیا جسے
حرزِ جاں بنا کے میں نے منزلیں طے کیں۔ آپ وہ وسیلہ ہو جس کے بغیر میرے قدم کبھی
اٹھ نہ سکتے۔ پر آپ کبھی خود پر منکشف نہ ہو سکے ۔ آپ کو اپنی قدر کرنی نہ
آئی۔۔۔۔۔ پارس ہو۔۔۔ جسے چھُو لیا اُسے کیا سے کیا بنا دیا‘‘
’’ہیں ۔۔۔ میں نے؟‘‘ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔
’’ہاں آپ نے
!‘‘
’’بات کو ٹالنا کوئی تم سے سیکھے۔ جو خود شہابِ ثاقب ہے
اور قرنوں سے بے کنار خلاؤں میں آوارہ پھرتا ہے اسے تم پارس کہہ رہی ہو۔ خوب مذاق
ہے بھئی‘‘ میں ہنس پڑا۔
حضرت رومی ؒ فرما گئے۔ عشق اول در دلِ محبوب پیدا
شُد(عشق پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتا ہے)۔ جس جذبے کی جوت جگائے پھرتے ہیں ۔۔۔
اس میں میں نے آج تک کوئی کمی نہیں دیکھی۔ یہ کس کی دین ہے؟۔۔۔ آپ مغرور، ہرلحظہ
ڈوب جانے کے خدشے میں مبتلا، شکوک وشبہات سے لبریز اور بیزار تھے۔۔۔ پھر یہ عجز،
یہ بے خوفی، یہ یقین اور یہ طلب کہاں سے آئی؟‘‘
(جواب تو آپ تھیں خانم۔ میں کیا کہتا۔ آمنہ خود واقف تھی)
آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔
’’روئیے مت فہیم۔۔۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے‘‘ روتی ہوئی آمنہ
نے اپنی بے قابو تمکنت سے کہا۔
’’بہتیرے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنا قفس ہمراہ لیے
پھرتے ہیں ۔ اپنے زنداں سے رہائی کس طور ملتی ہے ۔ میں نہیں جانتا ۔ میں تو جس طلب
کا قتیل ہوں اس سے بھی ہنوز آشنا نہیں ۔پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟‘‘
’’آپ ان میں سے ہیں جن کی تپش نگہ سے بستیاں بھسم ہوجاتی
ہیں اور جن کا نقش اگر ثبت ہو جائے تو موت کی لذت بھی سوا ہو جاتی ہے ۔ نسبت بڑی
چیز ہے فہیم ۔ ضروری نہیں کہ ہر متمنی کو اس کا مقام بتا دیا جائے۔ مراد اپنے
ضرورت مند کو جس طرح خود دریافت کرتی ہے اسی طرح فیض رساں بھی بنا دیتی ہے ‘‘ ۔
دفعتاً اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اوربولی:
’’میں برسوں سے یہ کرامت دیکھتی آرہی ہوں ‘‘
میں سراسیمہ اُسے دیکھتا گیا۔
’’آج یومِ وصیت ہے۔ وعدہ کیجئے۔ اپنی طلب کی شدت میں
کبھی کمی نہ آنے دیں گے ۔اس آگ کو کبھی مدہم نہ ہونے دیں گے۔ وعدہ کیجئے!‘‘
’’کیا میں اس لائق نہیں کہ تمہیں اپنے لیے زندہ رکھ سکوں
؟‘‘
’’کوئی بچھڑتا نہیں ہے فہیم۔۔۔ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے
درمیان ۔ ہاں حد سے زیادہ قیام کی مہلت سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ۔۔۔ یہ
بڑی سعادت کی بات ہے جنہیں وصیت چھوڑ دینے کی رعایت مل جائے‘‘
’’اپنے الفاظ واپس لو آمنہ۔۔۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے‘‘
میرے اندر کا بچہ مچل اٹھا۔
’’آج مجھے بولنے دیں ‘‘ اس کے چہرے پہ سارے بدن کا خون
سمٹ آیا اور آنکھوں کے سرخ ڈورے مزید سرخ ہو گئے اور جسم تھر تھرانے لگا۔ مجھے لگا
زمین سرک گئی ہو۔ ‘‘مریم کی رضا کا خیال رکھےئے گا۔ ۔۔ اسے اپنی زندگی جینے کا
اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ملا۔ وہ کسی کی امانت ہے ۔جب وقت آئے تو اسے سونپ دیجئے
گا۔ میں نے اپنی لحد کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ میری خاک کا خمیر یہیں سے
اٹھا تھا۔ اپنی ماں کے پہلومیں دفن ہونا چاہتی ہوں ۔ مجھے ماں کی آغوش نصیب نہیں
ہوئی ۔ مجھے جنم دے کر انہوں نے آنکھیں موند لیں تھیں ۔ سمیعہ خانم، جن کے خصائلِ
حسّنہ کے قصے میں اپنے والد ضرار احمد خان سے سنتی رہی۔ وہ شاعر، مصّور اور عمدہ
موسیقی کی شائق تھیں اور حضرتِ رومی ؒ کے دیس سے آئی تھیں ۔ اپنے محبوب شوہر کے
ساتھ ۔ میرے والد جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ متحدہ ہندوستان کی فوج میں
لفٹین تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اپنے بدیسی آقاؤں کا حکم ماننے سے اس لیے
انکار کر دیا کہ مقابل اپنے ہم مذہب تُرک تھے۔ خلاف ورزی کی سزا موت تھی اور وہ
فرار ہو گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔بَرِعظیم منقسم ہو گیا تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے
ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے ۔ ہمارا یہ چوبی آشیانہ میرے ماں کے خلاق ذہن کا شاہکار ہے
۔ میں اسی گھر میں اپنے والدین کی شادی کے بارہ برس بعد پیدا ہوئی ۔ اپنی عزیز اور
محبوب شریکِ حیات کی اکلوتی نشانی کی میرے والد نے بیس سال تک ہر خواہش اور ضد
پوری کی۔ ہتھیلی کا چھالہ بنائے رکھا۔ میں اپنی ماں کا ہُو بہُو عکس ہوں ۔ ۔۔۔ جن
دنوں آپ پہلی بار یہاں آئے تو میں ایک انوکھے جذبے کی آنچ پر پگھلنے لگی۔ اس کیفیت
کا اظہار میں نے مکمل صداقت سے اپنے والد کے رُو بہ رُو کیا۔ اُن کو بھی آپ بھا
گئے تھے ۔ مگر آپ اپنے آپ میں نہ تھے ۔ اور میرا یہ حال کہ جن دیواروں کو روز
دیکھتی تھی ۔ ۔۔ ان میں رنگ ہی رنگ بھر آئے ۔ بدن پر لگتا ہزاروں آنکھیں ابھر آئی
ہیں ۔ جس سمت دیکھتی ایک ہی میلہ نظر آتا۔ جذبے بدل گئے۔ عجیب عجیب سے خواب دیکھنے
لگی۔ آپ کا قیام لمحاتی تھا۔ کوئی فیصلہ صادر کےئے بغیر آپ پلٹ گئے اور میں نے آپ
کو عقب سے پکارا۔ آپ ٹھٹھک کے رکے اور میں نے وہ سب کچھ سنا ڈالا جو میں محسوس کر
سکتی تھی۔ آپ تو اس دن جنگل میں غروب ہو گئے خود میں نصف النہار پر جا ٹھہری ۔ پھر
ایک خواب دیکھا اور انہیں دیکھا جنہیں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا ہی جمال آفریں
صورت تھی۔ مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ بھینچا اور تادیر اپنی نگہ کے محیط میں رکھا۔
میری کایا کلپ ہو گئی۔ جاتے جاتے فرما گئیں:’’وہ پلٹ کے آئے گا جو ڈوبنے سے ڈرتا
ہے‘‘ ایسا ہی ہوا اور آپ آگئے۔ دور اس نشیبی خطے اور جنگل میں سے گزر کے جس میں آپ
برسوں پہلے غروب ہوگئے تھے۔ یہی جگہ تھی۔ اسی زینے پر بیٹھی تھی۔ ایسی ہی بارش
تھی۔ آج جیسا ہی موسم تھا۔۔۔ اور آپ اچانک ہی میرے مقابل آگئے تھے۔ وقت کتنی جلدی
بیت گیا فہیم‘‘
’’کاش ہم وقت سے بے نیاز ہُوا کرتے ‘‘ میں مسلسل رنج سے
مغلوب ہو کے بولا۔
آمنہ معّطر اگربتی کی طرح اپنے اختتامی سرے پر سلگ رہی
تھی۔ سرِمژگاں آنسوؤں کے دیپ ٹمٹماتے تھے۔ بھنور میں گھِرا ہوا انسان دائرے میں
گھومتا ہچکولے کھاتا ہے اور چشمِ اجل مسکراتی ہے ۔ گزرے ہوئے واقعات کی یادیں
دراصل شیشۂ ذہن پر کھینچی ہوئی خراشیں ہیں جو ماتھے کی جلد تلے چھپ کر تفکر ، تردد
اور غم کے تجریدی مرقعّے بن جاتی ہیں ۔ عمرِ رفتہ کے اوراق پلٹتی آمنہ کی پیشانی
پر کچھ ایسی ہی علامتی کہانی ابھر رہی تھی۔ وقت کا مغنی سوز کے دف پر تھاپ دیتا
گزررہا تھا اور چوبی زینے پر تھکے ہوئے دو رقاص بیٹھے تھے جن کی سانسیں حلق میں
معلق ہو گئی تھیں ۔
’’آقا حضور نبی کریم ﷺ نے ایک عربی شاعر لبید کے اس شعر کی بہت تعریف کی تھی ‘‘
الا کل شیئی ما خلا اللہ باطل
وکل نعیم لا محالۃ زائل
(خبر دار! ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ باطل نہیں
اور دنیا کی ہر قسم کی نعمت ختم ہونے والی ہے )
فہیم! بہت سی آرزوئیں کی تھیں اگر وہ درست ہوئیں تو اچھی
ہوں گی ورنہ ہم نے کافی زمانہ عیش و عشرت میں گزاردیا۔ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ
کے لیے محبت کی اور اس طریق پر چلنا میرے لیے سہل نہ تھا اگر خانم کی رہنمائی نصیب
نہ ہوتی اور آپ کا وفورِ عشق کا انداز میرے لیے مثال نہ ہوتا۔ آپ نے خانم کو ان کے
ظاہری جاہ وحشم کے ساتھ دیکھا ہوگا اور دل میں جانے کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے ہوں
گے۔ ان کی وجاہت اور حسن میں کوئی شک نہیں البتہ ان کی امارت سراسر مشاہدہ ہے اور
بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تامرگ مجاہدہ ہوتا ہے ۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ
وہ کسی کو شان و کروفّردے کے آزماتا ہے اور کسی کو خاک بسری دے کر۔ یہ دونوں راہ
کی منزلیں ہیں ۔ جو اللہ والے ہوں تو وہ مقامات سے فانی اور احوالِ ظاہری سے نجات
پائے ہوئے ہوتے ہیں ۔ حضرت اماں رابعہ بصری ؒ یوں ہی تو آگ اور پانی لے کر نہیں
نکل پڑی تھیں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور جہنم کو بجھا دیں تاکہ لوگ جنت کی لالچ اور
جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت نہ کریں ۔ بلکہ خالصتاً اس کی رضا کی خاطر عبادت
کریں۔ جو اللہ کی محبت کے گرویدہ ہوں ان میں کچھ تو اس کے انعامات واحسانات کے عوض
محبت کرتے ہیں اور بعض احسانات وانعامات کو اللہ کی دوستی کے غلبے کی بہ دولت حجاب
کا سبب جانتے ہوئے راہِ نعیم کو مقصود و مطلوب ٹھہراتے ہیں ۔ محبت عطائے ربانی ہے
۔ یہ نہ تکلف و اہتمام سے دل میں لائی جا سکتی اور نہ جبر سے نکالی جا سکتی ہے ۔
جناب داتا ہجویریؒ نے کیا خوب فرمایا کہ دل کی ترکیب اضطراب سے بنائی گئی ہے ۔ سو
سب سمندر دل کے سامنے سراب ہیں ۔ ہر وہ دل جو محبت سے خالی ہو بے کار اور مردہ ہے‘‘
آمنہ اس سمے وہ تان تھی جو بلند ہوئی اور اپنی اثر
آفرینی کو پھیلا کر واپس سَم پر آٹھہری تھی۔ اس کے سولہ ماترے میں نے ہمہ تن گوش
بن کر سنے۔ یہ راگ کیدارا نہایت میٹھا، مدھر، دل کو چھو لینے والا اور فرقت کو
ابھارنے والا تھا۔ پریم کی دھیمی آنچ پر وہ موم کی مانند پگھلتی آئی تھی۔ ۔۔۔ اب
شمع دان سے سوز کا دُھواں اُٹھ رہا تھا۔
بارش رُکی، دھوپ نکلی اور ڈھل بھی گئی۔ شام دبے پاؤں آئی
اور برقی چراغ روشن ہوگئے۔ ہم تشنہ اور ناآسودہ اُٹھے اور لرزتے جذبات کے ساتھ
سنگی روش پر چلتے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ بالائی منزل کی بالکونی میں بیٹھی
مریم آئندہ کے زمانوں میں کھوئی ہوئی دیکھی گئی۔ اس کی ریشمی شال کا پلو فاتح لشکر
کے پرچم کی طرح لہرا رہا تھا۔
-----------------------
(۱۴)
خانم!
پھر یوں ہوا کہ آمنہ ہم میں نہیں رہی ۔ عجیب بے مہر لمحہ
تھا جو ایک وجودی برہان کے ساتھ موت کا سندیسہ لایا اور آمنہ نے کمال تسلیم و رضا
کے ساتھ رختِ سفر باندھا اورمسکراتی ہوئی اجنبی منطقوں کے باحجاب موسموں میں چلی
گئی۔۔۔ اور پیچھے رہ گئے ہم باپ اور بیٹی ۔ پیچھے رہ جانے والوں کے پاس رہ ہی کیا
جاتا ہے۔ سوائے اشکوں کے جو صبح شام آمنہ کے تعویزِ مزار پر گرتے رہے، تحسینِ وفا
کی صورت۔ اپنی بے پایاں محبت کی نذر صرف اسی طور ہم دے سکتے تھے۔ ہمارے آنسوؤں کا
صحیح مسکن سینۂ زمیں ہی ہے کہ یہ نہ رخساروں پہ ٹھہرتے ہیں اور نہ پتھروں میں جذب
ہوتے ہیں ۔
وہ اپنی عزیز ماں کے پہلے میں جا سوئی، کسی معصوم شیر
خوار کی طرح جس میں تادیر جدائی کی تاب نہیں ہوتی۔
اس کی موت سے ہم نے جانا کہ دوامِ تمنا سراب ہے ۔ صرف
خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ۔ تب ایک الگ نم سے ہماری آنکھیں معمور رہنے لگیں ۔
تاریکیاں نور رہنے لگیں ۔
فرقت کا غم اتنا کڑا ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے لیے حرفوں
کی زنجیر بن نہیں پاتی ۔ قلم کے قدم راستہ چھوڑ دیتے ہیں ۔ میں آج تک آمنہ کے کہے
گئے لفظوں کی تعبیر ، لہجے کی تفہیم ، نگاہ کی تفسیر اور خوابوں کی تجسیم سے نہیں
نکل پایا۔ اپنی مرضی کی دُھن مجھ میں نہیں جاگی۔ اسی کی لگن کی لَے میرے بدن کے ساز
پر بجتی آئی تھی ۔ آپ نے خانم میری روح کو ساز بنا دیا اور آمنہ کی الفت کو دُھن
۔۔۔ جو گم ہو گئی اور سازابھی تک تھرتھرا رہا ہے۔ ہمارا ساتھ ادھورا رہ گیا۔۔۔ اور
ادھوری تصویر صدیوں کے مشاہدے سے بھی مکمل نہیں ہو سکتی ۔
تقدیر کا کہانی کاراور ہدایت کار کسی کردار کے مشورے اور
مرضی کا پابند نہیں ۔ جو اس نے لکھ دیا اور جوطے کر دیا، بس وہی ہوتا ہے ۔ زیست کی
تمثیل میں ہر کردار اپنے لکھے کا زندانی ہے ۔ اتنا ہی پیش کرتا ہے جتنا ہدایت کار
چاہے۔ جو ذرا بھی کھسکا تو اسے بلا یا جاتا ہے ۔ کڑی تنبیہ اور سرزنش کے ساتھ ۔
جینے کا ناٹک تو حقیقت میں مرنے سے بھی دشوار ہے ۔ ہم جو جیتے جی مر جاتے ہیں تو
ہدایت کار کہتا ہے : ’’کٹ! یہ کوئی مرناہے؟ نو ٹنکی کرتے ہو۔ ری ٹیک۔۔۔۔
کیمرہ۔۔۔۔۔ لائٹس آن! چلو پھر سے مرکے دکھاؤ۔ تاثرات حقیقی ہوں ۔ حرکات و سکنات
میں کوئی ریا کاری نہ ہو۔ اپنے مرے ہوؤں کا تصور کرو کہ وہ کہاں گئے۔ ذرا سوچو کہ
واقعی مر گئے ہو۔ اپنی نیت ٹھیک کرو کہ ہر عمل کا دارومدار اسی پر ہے ۔۔۔ لیکن
نہیں ! تم مرنا ہی نہیں چاہتے ۔ جیب اور پیٹ بھرا ہوتو فنا کا خیال کیسے آئے۔ اسی
لیے تمہاری اداکاری میں جان نہیں پڑ رہی۔ ۔۔۔ خاتمے کے بارے مت سوچو۔ کہانی میں نے
لکھی یا تم نے؟ چاہوں تو ایک دورانیے میں نپٹا دوں ، چاہے سلسلہ وار چلنے دوں ۔
تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم تھے ہی کیا؟ جو ہو تو کیا ہو؟ محض
کردار۔ جب چاہوں گا تمہیں مار دوں گا۔۔۔ ایک دن سارے کھیل کا پردہ بھی میں ہی گِراؤں
گا‘‘
آمنہ کا کردار ختم ہو گیا تھا۔ اسے وجودی موت دے دی گئی
تھی ۔
ہم ابھی تک ریہرسل میں مبتلا ہیں ۔کہانی جاری ہے ۔ سب
پردہ گرنے کے منتظر ہیں ۔
میں نے آمنہ کی موت کو تسلیم نہ کیا، تب تک کہ مجھے وہ
تجربہ نہ ہو گیا جب کوئی زمین پر چلتے چلتے اچانک پانی پر قدم رکھنے لگے تو بری
طرح کھٹک جائے اور سنبھلتے سنبھلتے بھی گرِ جائے۔ جینے اور مرنے میں خاک و آب جیسا
فرق ہے ۔ عجیب دلدلی سی سچائی ہے ۔
زیست ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی دم ساز سہارے کی محتاج ہوتی
آئی ہے ۔ اتنی عادی ہو جاتی ہے کہ قبر میں بھی اترے تو کندھے سے ہی اترتی ہے ۔
خنک بارچشموں سے کچھ دُور وسیع سبزہ زار جس میں اگر کچھ
نمایاں دِکھتا تو وہ سفید وسرمئی سنگِ مرمر کی بنی قبریں تھیں جن میں آمنہ کی قبر
باقیوں سے مانوس ہو چکی تھی ۔ یہاں چند صنوبر کے قدیمی پیڑ بھی تھے جن کی شاخیں
تجریدی مصوّری کی قوسوں کی مانند ابھرواں ، خمدار اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں
کی طرح تھیں جن پر ہر نوع کے پرندے نغمہ سنج تھے۔ اس افسانو ی نوعیت کے گورستان کے
مکینوں کا ذوق بھی کبھی یہی رہا تھا جو موسیقی ، مصوّری، علم، ادب اور دیگر جمیل
فنون کے رسیا تھے۔ قدرت کی وسیع الظرف فیاضی رُکی نہیں تھی۔ فیض رواں تھا۔
مجھے کافی تعطل کے بعد ایک مکتوب ملا۔ عبارت جانی پہچانی
تھی۔ میں نے اسے آمنہ کی لحد پربہ آوازِ بلند پڑھا:
’’سانحے اور صدمے گھر اور گور کو یکساں طور پر متاثر
کرتے ہیں مگر استقامت کو شکستہ پائی سزاوار نہیں ۔ قیام کی بہ جائے کوچ کے لیے ہر
لخطہ تیار رہو کہ یوں روح کوزنگ نہیں لگتا اور یہ آئینہ اندھا ہونے سے مامون رہتا
ہے ۔
یہ پیغام ہمارے الٹے سفر کا نشان تھا۔کسی اور دیس کی
جانب ہجرت کی حکم آپہنچا تھا۔مریم اس خوابِ زار میں اپنی محبوب ماں کی ابدی خواب
گاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ خط کی عبارت پڑھ چکا تو میں نے اس کے آنچل سے ڈھکے سر
پر دستِ شفقت رکھا اور کہا:
’’اُٹھو بیٹا! چلیں‘‘
اس نے مزار پر ملائمت سے ہاتھ پھیرے گویا صاحبۂ مزار کی
غیر مرئی زلفوں کو سنوارا ہو پھر قدرے خمیدگی کے ساتھ لوحِ مزار کو رم کر ایستادہ
ہوئی تو پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی ترکی باداموں جیسی آنکھوں میں اندوہ کا
رُکا ہوا سیلاب دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیلِ اشک بہہ نکلا ۔ ہچکیوں کے وقفے میں
ایک ہی لفظ ’ماں‘ کی تکرار تھی۔
اچانک کہیں سے بہت سی تتلیاں آگئیں اور آمنہ کی قبر پر
منڈلانے لگیں ۔
’’صبر۔۔۔ میری بچی ۔۔۔ صبر!‘‘ تجربہ نہ ہو تو دلاسا دینا
کتنا دشوار ہوتا ہے ۔ مجھے کوئی اسلوبِ تسلی معلوم نہ تھا۔ ناچار میں نے اپنی
لرزاں استقامت کو اپنی بیٹی کے شانے کے سپرد کر دیا ۔زندگی ہمیشہ سے سہارے کی
محتاج ہوتی آئی ہے ۔
(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)
(۱۵)
درختوں کے نیچے خزاں رسیدہ پتوں کا زرد سونا بکھر رہا تھا کہ حکیم
نشتر انصاری سفر کے ایک ایسے مرحلے میو ملے جب ہم نے اگلی منزل کے لیے گاڑی بدلنی
تھی۔
وہ جس والہانہ پن سے ملے اس نے بیتے دنوں کی یاد تازہ کر
دی ۔ ہمارے ساتھ آمنہ کو نہ پا کر ان کی شہرۂ آفاق ہنسی بھاپ بن کر اُڑ گئی۔ وہ سب
کچھ بھانپ گئے۔
’’اے ساکنِ وادئ دلدار! کچھ اُدھر کی سنائیے؟‘‘ میں نے
پوچھا۔
’’ارے میاں! کچھ نہ پوچھو۔ زلزلے کا مرکز کہیں بھی ہو
مگر اثر کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے ۔ بھائی نورو بھی چل بسے۔ محبوب کی کوئی خبر
نہیں ۔ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ماسٹر خوشحال سنگھ اپنے پوتے پوتیوں
کے ہاں تھائی لینڈ سدھار گئے۔ حافظ شمسی کی بینائی مکمل طور پر رخصت ہو گئی۔ موہن
داس کا کفر خدا خدا کر کے ٹوٹ گیا، عبدالرحمٰن بن گئے اور خدیجہ سے نکاح کر کے
دونوں سُوئے طیبہ روانہ ہو گئے۔ محرم کے بغیر ویزہ نہیں مل رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے
کہ موہن داس ، خدیجہ کے عشق میں مبتلا چلے آئے تھے ۔ قدرت بھی زبردست حکمت والی ہے
۔ ملایا بھی تو کیسے ۔ کیا نصیب پائے ہیں دونوں نے ۔ آپ نے اپنا گھر جوخدیجہ بہن
کو تحفتہً دیا تھا، وہ دارُالمطالعہ بنا دیا گیا۔ ۔۔۔ اسی لائق تھا۔۔۔ بہت پر سکون
جگہ پر ہے ناں۔ مائی خیراں اس کی منتظم ہے ۔ میں نے اپنا ذخیرۂ کتب اس کے لیے عطیہ
کر دیا۔ مزید کتابیں خوشحال سنگھ نے دیں ۔ کچھ منگوائیں بھی ۔ میں پچھلے کئی دنوں
سے چکر میں ہوں ۔ اور آپ لوگ؟‘‘
’’قصۂ غم طویل ہے‘‘ میں نے افسردہ طمانیت کے ساتھ کہا۔
حکیم انصاری کچھ دیر مجھے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتے رہے پھر بڑی گھمبیر آواز میں
بولے :
’’کوئی وقت جاتا ہے کہ بزمِ ہستی اُجڑ جائے گی ۔ اپنی
ساری عمر ضد میں گزری ۔ اب تسلیم کی عادت پڑنے لگی ہے ۔ ضد اختیاری تھی تو تسلیم
سراسر توفیق ہے ۔ مجھے فلسفے نے گمراہ کیئے رکھا۔ احکاماتِ اور فرائضِ شریعت پر جب
سے دیانتدار انہ غوروفکر کرنا شروع کیا تو پتہ چلا، فلسفہ تو ان کے آگے پانی بھرتا
ہے۔ فلسفہ عشق کی تفسیر کبھی نہیں کر سکتا۔ نورو کی موت سے چند دن پہلے ان کی ناؤ
میں بیٹھا تو بڑی زور دار بحث ہوئی تھی ۔ اس دن وہ جلال میں آئے ہوئے تھے۔
ناخواندہ تھے۔ لیکن علم کے معاملے میں ان سے میں بُری طر ح مارکھا گیا۔ کہنے لگے
کہ کس دنیا میں رہتے ہو۔ خود تو گھاس کی ایک پتی ایک ذرۂخاک یا خلیۂ انسانی تک
بنانے پر قادر نہیں اور تصرف کرتے ہو قادرِ مطلق کے معاملات میں ۔ خدا کی شان ۔۔۔۔
بت مسلمان ہونے جا رہے ہیں تو یہ حضرت کافری پر بہ ضد ہیں ۔ ان دنوں موہن کی نورو
سے گاڑھی چھننے لگی تھی ۔بعد میں جلد ہی موہن نے ان کے ہاتھ پر بیعتِ دین کی اور
عبد الرحمٰن ہوئے ۔ ان کے دلائل نے میرا سینہ شق کر دیا اور میرے زعم کے چیتھڑے
اُڑادیئے۔ علمِ معرفت کے آثار کے پورے جانکار تھے ۔ میں نے لاجواب ہو کر سپر ڈال
دی تو بولے۔ مہلت جتنی بھی ملے اسے غنیمت جانو۔ ازالے کی نیتِ صادق بھی نجات کے
لیے کافی ہوتی ہے ۔ لہٰذا فہیم میاں ! چکر میں آیاہُوا ہوں ۔ حادثے اور خوشیاں
کبھی التوا میں نہیں رہتیں ۔ ہر وقوعہ اپنے متعینہ زمانی چوکھٹے میں تصویر ہو جاتا
ہے ۔ اسباب و علل اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں ۔ نتائج کو مانے بغیر جان نہیں
چھوٹتی۔ میں نے ساری عمر قیام کیا اب کوچ پرمامو ر کر دیا گیا ہوں ۔ کسی کا حکم ہے
کہ روح کو زنگ لگوانے سے بہتر ہے ، گردش میں رہو۔ پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی
گئی ہے تو میں بھی اسے بہ ہر طور نبھاہنا چاہتا ہوں ۔۔۔ لیکن آپ کہاں کا قصد کیے
ہوئے ہیں ؟‘‘
’’جہاں قسمت لے جائے‘‘
’’لگتا ہے بساط سمیٹی جا رہی ہے ؟‘‘
’’پیادوں کی مجال ہی کیا ‘‘
’’ٹھیک کہتے ہو میاں! نہ مجنوں رہے گا اور نہ ویرانہ‘‘
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(۱۶)
موسم کی پہلی برف باری کے بعد سارے ماحول کو برف کے کفن
نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لُنج مُنج درختوں کے پتے آنسو بن کر جھڑ چکے تھے۔
ریل گاڑی اجنبی خطے سے گزر رہی تھی ۔ سورج کی کرنیں برف
پر سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں ۔ بہت کچھ تیزی سے گزر چکا
تھا اور باقی گزر رہا تھا ۔ میرے کانوں میں کچھ عجیب سا شور سنائی دینے لگا حالاں
کہ گاڑی کے اندر مدہم ، خوابیدہ اور مخمور سی آوازیں تھیں جو ناگوار محسوس نہیں
ہوتیں ۔ وہ شور کچھ ماتمی سا تھا۔
مریم کھڑکی کے ہوا بند شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہی
تھی ۔ کچھ دیر پہلے تک ہم نے ساری رات باتوں میں گزار دی تھی اور دونوں ہی اپنے
اپنے لفظوں کے سکے خرچ کر چکے تھے۔
میں نے آنکھیں بند کیں تو کسی اور جہان میں جا کھلیں
۔حلاوتوں ، لطافتوں اور راحتوں سے نوبت مفارقتوں ، صعوبتوں اور تلخ صداقتوں تک
پہنچی تو میں نے سہولت سے پاؤں پسار لیے۔ وہ لمحۂ حال کے مرگ زار سے لمحاتی گریز
تھا۔ یادوں کے معمر چیتھڑے حُزن کی تند ہواؤں میں پھڑ پھڑانے لگے تھے ۔
برباد زمانوں کے ملبے سے تازہ جہانوں کی تشکیل ہوتی رہے
گی۔ برف پگھلی تو زمین نئے سبز پیرہن سے ڈھک جائے گی ۔ سفر اجسام کا ہو یا نظریات
کا جاری رہے گا۔
ریل برف پوش ساحلوں کوچھُو کر بہت بڑا قوس بناتی ہوئی
گزر رہی تھی اور پیچھے ننگی پٹڑی دھوپ میں چمک رہی تھی جیسے کوئی جسیم خمدار تلوار
پڑی ہو۔ بہت دُور سمندر میں سست برفاب موجوں کی جھاگ ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی
پانی میں ضم ہو تی تھی۔ حدِ اُفق تک پھیلا وہ دورنگی منظر نگاہ کی ترائی میں اتر
گیا۔
پھر چلتی ہوئی ٹرین کے دونوں اطراف پہاڑیاں نمایاں ہو
گئیں جو کہیں کہیں بغل گیر ہوتیں تو سرنگ کی تاریکی اور سناٹے کو تیزی سے کاٹتی
ہوئی ریل کی آواز گھونسے کی مانند دل پر لگتی اور ایک دبنگ احساس کو جگا دیتی ۔
ہر منظر ہمارا میزبان تھا ۔
ہر راستہ ہماری رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔
سفر کو ہم درپیش تھے ۔
منزل ہماری منتظر تھی ۔
اور جب دھواں دیتی برف بھری آبادیوں سے گزرتے ہوئے ایک
درمیانے درجے کے پہاڑی ریلوے سٹیشن پر گاڑی رکی تو ہم زادِ سفر سمیت اتر گئے ۔ ہر
مقام سے پہلے دل و دماغ کسی انجانی قوت کے زیر اثر آجاتے تھے ۔ کہیں بھی ٹھہرنے
میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔
وہاں جو مسافر اترے وہ جلد ہی اگلی منزلوں کی طرف چلے
گئے ۔ سٹیشن پُر رونق نہیں تھا ۔ ویران اور سنسان بھی نہ تھا۔ مریم کو بھوک لگ رہی
تھی ۔ کھلے اور طویل پلیٹ فارم کی ایک چوبی شکستہ بنچ پر میں نے مختصر سامانِ سفر
رکھا اور مریم کو بٹھا کر خود قریب ہی ایک ٹھیلے والے سے پنیر ، سلاد، پیزا اور
پانی کی دو بوتلیں خریدیں اور واپس بنچ پر آبیٹھا۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی کھانا کھا
رہے تھے تو مخالف سمت سے ریل کے انجن کی سیٹی سنائی دینے لگی ۔ اسی اثناء میں ایک
شور سا پھیل گیا۔ اگلے چند لمحوں میں سرخ پھندنوں والی ٹوپیاں پہنے بہت سے لوگ ایک
بے حد خوبصورت سنہری تابوت کو کندھوں پر اٹھائے آگئے۔ تابوت کو نہایت احترام اور
احتیاط کے ساتھ ایک بڑی سی میز پر رکھ دیا گیا۔ لوگ متواتر بڑھتے چلے آرہے تھے اور
تابوت کے گرد دائرہ پھیلتا چلا جا رہا تھا ۔ میں اپنے منہ کے نوالے کو حلق سے نیچے
اتار نا بھول گیا اور دائرے کی طرف بڑھا ۔ ریل گاڑی بھی آپہنچی تھی۔ میں نے بھیڑ
کو چیر کر تابوت تک پہنچنے کی کوشش کی اور آخر کامیاب ہو ہی گیا مگر یہ جاننا ابھی
باقی تھا کہ میت ہے کس کی ۔ مرد ہے یا عورت؟
ایک شخص سر جھکائے تازہ گلابوں کی چادر کو تابوت پر سجا
رہا تھا ۔ پھول اور اقسام کے بھی بہت سے تھے ۔ دفعتاً اس شخص نے سر اٹھا، ایڑیوں
کے بل کھڑے ہو کر کسی کو نام لے کے پکارا تو مجھے اپنے وطن کے ایک شہر کی فٹ پاتھ
’ایک پھیلا ہوا ہاتھ‘ چند ناقابلِ فراموش الفاظ اور برسوں پرانی شام یاد آگئی۔
میرے پاؤں شل ہو گئے اور دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
ریل گاڑی ادھر جا رہی تھی جدھر سے ہم آئے تھے۔
میں نے سرجھٹک کر خود کو فعال رکھنے کی ناکام کوشش کی ۔
اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کئے بغیر میں نے تابوت
پر سجی پھولوں کی چادر ذرا سی کھسکائی اور اپنے واہمے کا بطلان کرنے کی سعی میں
شفاف شیشے میں سے میت کا چہر ہ دیکھنے کو اپنی نظر اندر پھینک دی مگر جتنی تیزی سے
نظر اندر گئی ، پلٹ کر اتنی ہی سرعت سے آنکھ میں آٹھہری۔ ناچار پلکوں اور ہونٹوں
کا متحدہ بوسہ تابوت پر ثبت کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔
اس بھیڑ میں رؤساء، شرفا اور مقتدر طبقے کے دیگر افراد
کے علاوہ افتادگانِ سماج کی کثیر تعداد شامل تھی۔ ہر چہرہ ملول، رنجیدہ اور سنجیدہ
تھا۔ سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہُوا تھا۔
تابوت دوبارہ کاندھوں پر اٹھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے
گاڑی کے روشن کارگو کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا گیا۔ انجن کی وسل گونجی، بھیڑ چھٹنے لگی
۔ حتیٰ کہ جہاں تابوت رکھا ہوا تھا، اب اس جگہ صرف میں ہی کھڑا رہ گیا۔ ریل چل پڑی
تھی۔ وقتِ عصر ڈھل رہا تھا ۔ موسم کے تیور بدلنے لگے تھے ۔
مڑتے ہوئے نظر دفعتاً پلیٹ فارم کے فرش پر گرے ہوئے ایک
غنچۂ گلاب پر پڑی جسے میں نے اٹھا لیا اور مٹھی میں دبائے نڈھال قدموں کے ساتھ
مریم کی طرف بڑھا جو بنچ کے قریب کھڑی ریل گاڑی کے ہیولے کو دیکھے جاتی تھی ۔
’’لو بیٹا! ۔۔۔ اسے سنبھال کے رکھنا‘‘۔ میں نے غنچۂ گلاب
اسے تھماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ غنچے کی مہک سے جانے کیسے حقیقت پا گئی۔ بولی:
’’بابا! خانم بھی ہمیں چھوڑ گئیں ؟‘‘ اور بے پناہ بے چارگی کے ساتھ روتی ہوئی بنچ
پر گر گئی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔ختم
شد۔۔۔
واہ کینٹ
09نومبر2012ء
-------------------