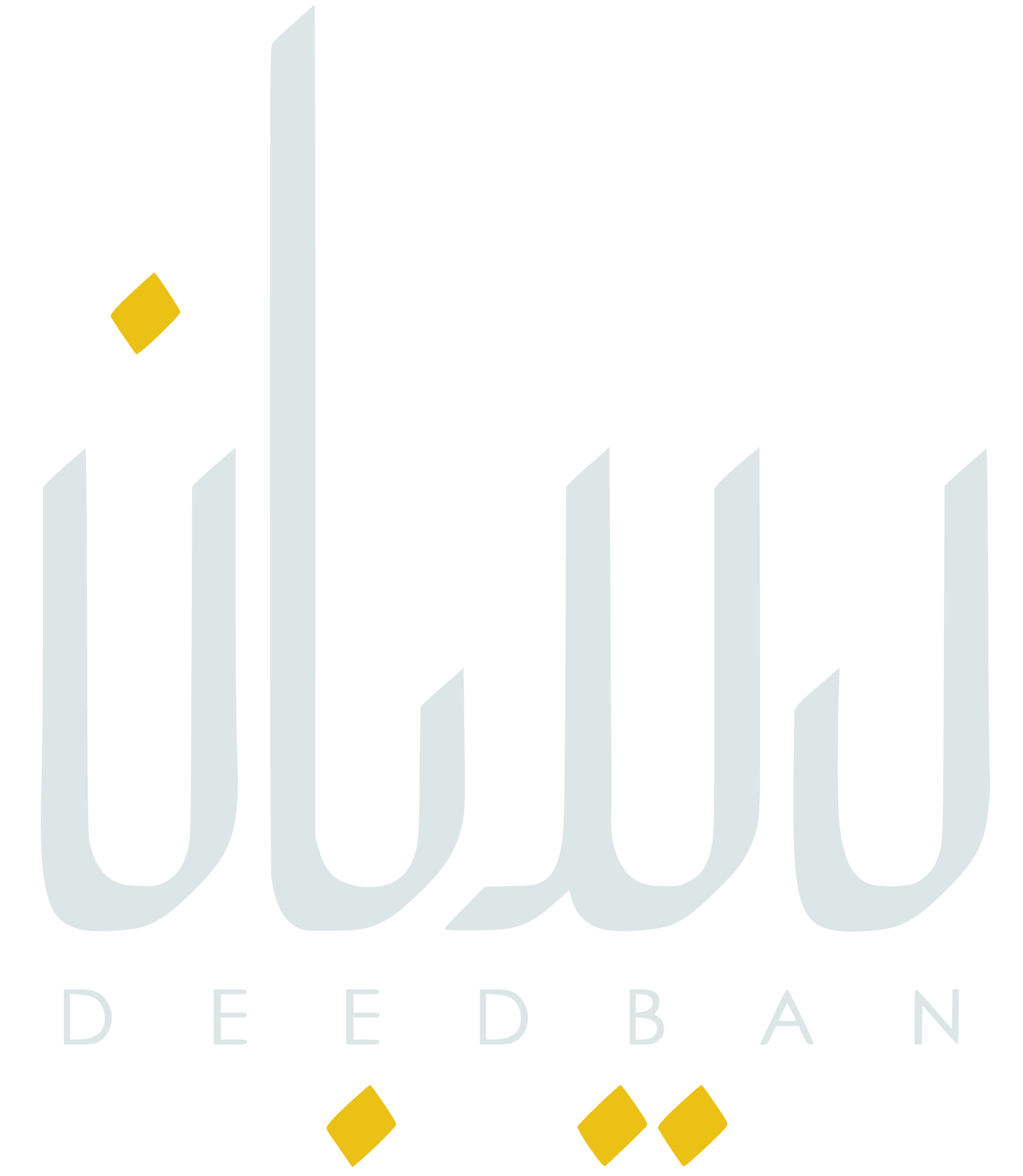بوڑھا نیم اور ماسٹر جی
بوڑھا نیم اور ماسٹر جی
Feb 19, 2022

بوڑھا نیم اور ماسٹر جی
تحریر: پروفیسر عامرزرین /کراچی
گاؤں میں ہمارے گھر کے صحن میں نیم کا بوڑھا درخت تھا۔ جہاں کبھی دو کالی اور ایک بھوری گائے باندھی جاتی تھیں۔ لیکن بعد ازاں نہ جانے کیوں یہ سب جانور بیچ دیئے گئے۔ اب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم تمام بچہ لوگ ناشتے کے بعد اس درخت کے نیچے بارہ بجے تک پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے۔ ابّا جی سرکاری اسکو ل ٹیچر تھے۔ ہمارے آس پڑوس سے بھی چھوٹے بچے اپنے بستے سنبھالے ہماری کمپنی میں آجاتے۔ اگرچہ ابّا جی کے پاس ان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا وقت بھلا کہاں تھا؟چلو ہمیں تو تھوڑا بہت پڑھا دیتے اور باقی رہی سہی کسر ہماری باجیاں پور ا کردیتی تھیں۔ابّا جی گاؤں کے سرکاری اسکول میں سینئر ٹیچر تھے لہٰذا اسکول کے انتظامی اور دفتری امورمیں مصروف رہتے۔ کبھی کبھار دفتری کام سے شہر بھی جانا پڑتا تھا۔
گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول کا کام کرتے ہوئے مجھے بہت مزا آتا تھا۔اسی لئے میں انہماک اور شوق سے پڑھائی کے کام میں مصروف رہتا۔سورج جیسے سوا نیزے پر آتا نیم کے درخت کی چھاؤں اور گہری ہو جاتی تھی۔بلکل ایلسا کیزی کی نظم ”دی نیم ٹری“ کے مطابق کہ”نیم سُورج کی دھوپ کے آگے ڈھال بن جاتی ہے اور سارا دن دھوپ برداشت کرتی ہے۔“ابّا جی اگر اسکول سے جلدی آجاتے تو کمرے میں بیٹھ کر لکھائی پڑھائی کے کام میں لگ جاتے۔ اگر کسی دفتری کام سے شہر چلے جاتے تو ہمیں اس با ت کی پوری اُ مید ہوتی کہ ابّا جی شہر سے واپسی پر تربوز یا پھر آم لائیں گے۔اگر ابّا جی یہ پھل لے آتے تویہ دوپہر کے کھانے کے بعدکھائے جاتے۔ سادہ زمانہ تھا نہ سیل فون نہ واٹس ایپ، فیس بُک، ٹوئٹر، بوٹیم، انسٹا گرام جیسی قیمتی وقت کھا جانے والی قباحتیں۔گرمیوں کی ہر دوپہر کھانے کے بعد سونے کے لئے ہوتی تھی۔اکثر بچوں کی کہانیوں والی کتاب پڑھتے پڑھتے نیند آجاتی۔ ہمارے گھر کے پیچھے مستریوں کی دُکان تھی جو ساری دوپہر لکڑی یا لوہے کے کام میں مگن رہتے۔ اس لئے کبھی لکڑی کاٹنے یا لوہا کوٹنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں اور اب ہم اس شور سے مانوس ہوگئے تھے۔ میں شام کے اوقات میں فٹ بال کھیلنے کے لئے گراؤنڈ کی طرف نکل جاتا۔ رات میں ہلکا پھُلکا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ کر سوجاتا۔ فٹ بال جیسی تھکا دینے والے کھیل کی وجہ سے نیند بھی جلد آجاتی۔
ہمارا پڑوسی کہنے کو تو گاؤں کے بچوں کو انگریزی نثر اور گرائمر پڑھاتے تھے۔ اُن کا نام شفاعت تھا۔ہم اُنہیں انکل جی لیکن گاؤں کے بہت سے لوگ اور اُن کے شاگرد انکل جی کو ماسٹر جی کہتے تھے۔ سُنا تھا بلکہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ رائل برٹش آرمی میں آفس کلرک تھے اور جنگِ عظیم دوئم میں برما اور بنگال کے محاذوں پر تعینات بھی رہ چُکے تھے۔اُن کی زبانی بنگال کی ارضی اور نسوانی خوب صورتی اور جادو کے قصے سُن سُن کر مَیں محظوظ بھی ہوتا اور کبھی خوفزدہ بھی۔ ایک دفعہ انکل شفاعت جنگ ِ عظیم دوئم میں ڈھاکہ کے محاذ پر شہر کے مضافات میں امدادی چیزوں کی ترسیل میں مصروف تھے۔اُن کے ہمراہ دوسرے فوجی بھی تھے۔ ایک بستی میں اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک گھر میں وہ ایک انتہائی خوب صورت اور پُرکشش عورت کو دیکھ کر دم بخود ہوگئے تھے۔اُس عورت کا حُسن ناقابل ِ بیان تھا۔اُس کے بال اماوس کی رات کی طرح سیاہ اور سوانا کے جنگلوں کے طرح گھنے تھے۔اُس کے سیہ بال اُس کی ایڑیوں کو چھوتے تھے۔یہ قُدرتی دین اُس عورت کے نسوانی خدوخال کو بڑھاوا دیتی تھی۔اُس عورت کی ایک جھلک میں عجیب سی سحر انگیز کشش تھی۔ انکل شفاعت اور اُس کے ساتھی اس عورت کو دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئے تھے کہ جیسے وہ اس زمین کی مخلوق نہ ہو کوئی اپسراء ہو۔ابھی یہ قصہ جاری تھا کہ انکل شفاعت کے ٹیوشن والے بچے آگئے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک بہت دل چسپ بلاک بسٹر فلم میں انٹرول آگیا ہو۔ لیکن کچھ خبر نہیں تھی کہ منقطع ہونے والا سلسلہ کب دوبارہ سے جُڑے گا۔مجھے تجسس کی اتھاہ کیفیت میں چھوڑ کر انکل شفاعت بچوں کو فعل ماضی مکمل پڑھانا شروع کاچُکے تھے۔ لیکن میرے لئے اُن کی باتیں فعل ماضی جاری کی حیثیت رکھتی تھیں۔
ماسٹر جی دو دن مصروف رہے اُن سے مُلاقات نہ ہوسکی میرے سوچ اور خیال بنگال کے سحر انگیز حُسن میں اُلجھے رہے۔یہ اسّی کی دہائی کا دور تھا۔ابھی گلو بل لائزیشن کے ہنگام ڈیجیٹل عہد کا آغاز نہیں ہوا تھا۔بلکہ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کی منازل سے بہت پیچھے اپنے بام ِ عروج کی طرف خراما ں خراماں ریس میں جیتنے والے سُست رو کچھوے کی طرح محو سفر تھی۔ اس لئے ممکن نہیں تھا کہ میں بنگال کے علاقائی رہن سہن اور روایات کے بارے میں معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کر پاتا۔اُس دوَر تک زبانی قصہ گوئی اور داستان سُنانے کی روایت اپنی اہمیت اور دل چسپی کے ساتھ جوان تھی۔لیکن شاید اب لوگو ں کے پاس اپنے ماحول اور اس میں موجود سانس لینے والے دوسرے انسانوں کے لئے وقت نہیں ہے۔تو پھر داستان گوئی کو کون خاطر میں لاتا ہے، اسی لئے سماجی رابطوں کو جوڑنے والی ایسی روایات متروک ہوچُکی ہیں۔
ہر رات ماسٹر جی کے پاس وقت ہوتا لیکن میں شام کی تھکا دینے والی مصروفیات کی وجہ سے جلد سوجاتا۔ ماسٹر جی کے پاس ایمبسیڈر کمپنی کا ایک ٹرانسسٹر ریڈیو تھا جو کہ فراغت کے اوقات میں اُن کا وفادار ساتھی تھا۔جنگِ عظیم کے ختم ہونے کے بعد آج تقریباً 35 برس کے بعد بھی ماسٹر جی اسی شوق اور فکر کے ساتھ بی بی سی سے سیربین بلاناغہ سُنتے کہ جیسے اس بُلیٹن میں جنگِ عظیم کے دوران کی تازہ صورتِ حال پر اپ ڈیٹ دیا جا ئے گا۔جرمنی کے پسپاہونے اور اتحادیوں کی مختلف مقبوضہ مُلکوں کی آزادی کے لئے پیش قدمی کی خبریں دی جائیں گی۔ حالاتِ حاضرہ کی خبریں سُن کر جب جب موقع ملتا وہ ہر ملنے جُلنے والے کے ساتھ یہ خبریں شئیر کرتے اور اس پر تبصرہ بھی فرماتے تھے۔ اگرچہ اُس دور میں شاید جھوٹ اور منافقت معاشرتی روایات میں اتنی سرایت نہ کرگئے تھے کہ میڈیا نیوز ڈپلو میسی پر انحصار کرتے۔ کہا جاسکتا ہے کہ کافی حد تک ایک شفاف اور مخلصانہ طرزِ زندگی تھا۔ اگرچہ عالمی سطح پر یہ سرد جنگ کا دور تھا اور مُلکی سطح پرتیسری مارشل لاء کا زمانہ تھا۔ تمام ابلاغ پر ضیائی مارشل لاء کا تسلط تھا۔ قومی ٹی وی کی کوئی خبر یا پروگرام سنسر شپ کے مراحل سے گذرے بغیر پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابّا جی اور ماسٹر جی مُلکی میڈیا کی خبروں پہ بی بی سی کی خبروں کو زیادہ معتبر مانتے اور ترجیح دیتے تھے۔
ماسٹر جی بزرگ تھے 70 سے زائد بہاریں دیکھ چُکے تھے۔برٹش رائل آرمی میں ہوتے ہوئے وہ اُس عظیم عالمی واقعہ کے چشم دید گواہ بھی تھے جب 1945 ء میں دوسری جنگِ عظیم دوران امریکی سامراج نے نامور سائنسدان البرٹ آئن سٹائن کے فارمولا کی بنیاد پر ایٹم بم بناکر جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگا سا پر اس مہلک ہتھیار کا عملی تجربہ کیا بلکل ویسے ہی جیسے ناگہانی کورونا ویکسین بغیر ٹرائل کے دُنیا بھر میں بالجبر لگائی جارہی ہے۔۔ اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زائد بے گناہ انسان ایٹم بم ٹرائل کا لقمہء اجل بن گئے تھے۔ ہر حساس انسان کی طرح یقینا ماسٹر جی کے لئے بھی یہ المیہ ناقابلِ فراموش تھا۔
ان تمام تلخ وشیریں ماضی کی یادوں کے باوجود ماسٹر جی بڑھاپے میں بھی ایک پُر اثر اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔جہاں ماسٹر جی بنگال کے حُسن سے متاثر ہوئے نہیں رہ سکے ہوں گے یقیناوہیں لمبے گھنے بالوں والی اپسراء کی دھڑکنیں ماسٹر جی کو دیکھ کر ضرور تیز ہوئی ہوں گی۔
میں نے جب ہوش سنبھالا تو ماسٹر جی کو تنہا ہی دیکھا۔ ہمارے گھر میں کبھی کبھار یہ بات سُننے میں آتی تھی کہ ان کی شریکِ حیات گھریلو انارکی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔مضبوط ارادوں والے فوجی کی دلیری، بہادری اور اناء ان کے جذبات اور خاندانی محبت پر غالب رہے۔نہ کبھی انہوں نے اپنی شریکِ حیات کو لانے کی کوشش کی اور نہ کبھی اُس بھاگوان نے گھر کی طرف لوٹ آنے ارادہ کیا۔سُنا تھا کہ کچھ عرصہ تک ماسٹر جی سرِ شام بس اسٹاپ پر جاکر ناراض لوگوں کی واپسی کا انتظار کئے کرتے تھے اور پھر مایوس ہوکر یقینا بھاری دل کے ساتھ لوٹ آتے۔
ماسٹر جی ہر رات آل انڈیا ریڈیو سے فرمائشی فلمی گانوں سے لُطف اندوز ہوتے۔خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں رات جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا تو اُن کے ٹرانسسٹر سیٹ سے انڈین فلمی گانوں کی آواز دُور دُور تک سُنی جا سکتی تھی۔ چند ایک گانے تو جیسے ماسٹر جی کے دل کی آواز تھے۔کیونکہ میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا محسوس کر سکتا تھا کہ جب جب وہ مخصوص گانے نشر ہوتے ماسٹر جی ریڈیو کی آواز تھوڑی اور بڑھا دیتے تھے۔ شاید وہ اپنے محسوسات اور کسی کی جُدائی میں اپنے ماحول کی ہر چیز کو شریک کرلینا چاہتے ہوں۔ایک گانے کے بول مجھے آج بھی یاد ہیں، جو کچھ ایسے تھے، ”……تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے ہائے…… ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے“۔ رات کی خاموشی میں یہ گانا واقعی کیا سماں باندھتا تھا کہ بہت سے ہجر اور جُدائی کے ماروں کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔اسی طرح چند اور انڈین فلمی ٹریک ماسٹر جی کے پسندیدہ تھے خاص کر جن میں انتظار اور انتظار میں محبت اوریاد کے موضوع پر شاعری ہوتی اور سونے پہ سہاگہ سادہ اور پُر تاثیر گلوکاروں کی آواز اور موسیقی عجیب سماں باندھتی تھی۔ وہ انتہائی سادہ زمانہ تھا، لوگ بھی سادہ تھے۔ ہم بھی اُس وقت تک قلبی وارداتوں کے اثرات سے آزاد تھے۔لیکن آج اس دور اور عمر کے اس پُختہ حصے میں ماسٹرجی کی قلبی کیفیت اور جُدائی کے دُکھوں کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔
چند سالوں میں جیسے جیسے میں تعلیم کے درجات میں آگے بڑھتا گیا، میرے لئے گاؤں میں رہ کر مزید تعلیم کا حصول ناممکن نظر آنے لگا تھا۔اِن مُشکلات کے پیشِ نظر بڑے بھائی جان نے مجھے اپنے پاس شہر میں بُلا لیا۔ پھریہ وقت آیا کہ گاؤں سے دور ہوئے اور پردیس نے اپنے پھیلے بازؤں میں پناہ دی۔مَیں نے خُود کو شہر کے تیز، چالاک، ہوشیار، کہیں مخلص تو کہیں خود غر ض اور لالچی لوگوں میں پایا۔ گاؤں کے سادہ اور سیدھے سادھے لوگ، اُن کی باتیں اور یادیں سب دُھندلی پڑنے لگیں۔ کالج میں داخلہ لیا۔ نیا ماحول نئے دوست،زندگی میں نئے چیلنج اور ایسے ہی دن بدن اور ماہ بہ ماہ گاؤں کے لوگوں سے دُوری اور لاتعلقی بڑھتی گئی۔لیکن شہر میں شہر کے لوگوں میں اپنی پہچان ضرور قائم رکھی کہ میرا تعلق گاؤں سے ہے۔ترقی کی منازل کی طرف گامزن گاؤں سے سماجی رابطے جیسے دُھندلا ساگئے۔اِن راستوں پہ جیسے گھاس اُگنے لگی۔خط و کتابت کا سلسلہ تھا تو صرف اپنے گھر والوں سے۔ اُس وقت گاؤں میں ٹیلی فون نام چیز کا وجود تک نہ تھا۔کالج سے فارغ ہوا تو گھر والوں کے اسرار پر گاؤں جانے کا پروگرام بنایا۔خیر اپنی جنم بھوم کی طرف محوِ سفر ہوا تو گاؤں کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔مجھے گرمیوں کی چُھٹیوں کے دن یاد آرہے تھے جب بوڑھے نیم کے درخت کی چھاؤں میں ہم سب بہن بھائی اپنے اسکول کا کام کیا کرتے تھے۔آس
پڑوس کے بچوں کے چہرے بھی ایک ایک کرکے میری نظر میں آئے جو ہر صبح اپنے بستوں اور کتابوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھائی میں شریک ہوجاتے تھے۔ یادوں کی بیاض کے دفتر میں ماسٹر جی کا باب بھی کُھلا۔ وہی ہر شام بی بی سی کے نیوزبُلیٹن،وہی رات گئے آل انڈیا ریڈیو پر فرمائشی فلمی گانوں کا پروگرام، جس کے کچھ سحر انگیز گانے مجھے لوری دے کے سُلا دیتے تھے اور دوسری طرف ماسٹر جی کی جُدائی کے زخموں کوہرا کردیتے تھے۔
میں بعد از دوپہر گھر پہنچا۔سفر کی تھکاوٹ بھی تھی اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک بے رونقی اور ویرانی کا احساس ہوا۔صحن بھی خالی خالی اور کُشادہ لگا۔ نیم کا درخت اپنی جگہ موجود نہ تھابلکہ اب وہاں شیشم کے دودرخت جنہیں میں نے کچھ برس پہلے بہت چھوٹے چھوٹے دیکھا تھا لیکن اب وہ اپنی جڑوں کے ذریعے زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرچکے تھے۔میرے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ ایک شام تیز اور طوفانی آندھی نے نیم کے درخت کو جڑ سے اُکھاڑ دیا۔آخرِ کار اُسے یہاں سے ہٹانا ہی پڑا۔
اس بار میرے گھر کے پڑوس میں ایک وحشت انگیز سکوت تھا، ایک خاموشی تھی۔میرے استفسار پہ کہ ماسٹر جی کا ریڈیو آج کیوں خاموش ہے؟ میرے ابا جی نے بتایا کہ تمہیں خط میں بتایا تو تھا کہ چند ماہ قبل ماسٹرجی حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے عدم سدھار گئے۔شہر کی مصروف زندگی اور تعلیمی سرگرمیوں کے باعث شاید میں اس خبر پر توجہ نہ دے سکا تھا۔لیکن مجھے اس وقت یہ خبرسُن کرانتہائی صدمہ ہوا۔ماسٹر جی کا آخری وقت کچھ اس طور اٹل اور مختصر تھا کہ اُنہیں ہسپتال لے جانے کہ مہلت بھی نہ مل سکی۔وہ شام بہت عجیب تھی۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔لیکن نہ تو مارک ٹلی کی خبروں کا بُلیٹن، نہ ہی فرمائشی فلمی گانوں کی آواز،نہ ہی نیم کے پتوں کی سرسراہٹ اور نہ ہی نیم کے بُورکی مسحورکُن خُوشبو تھی۔ مجھے ماسٹر جی اور نیم کے بوڑھے درخت سے بچھڑنے کا انتہائی افسوس تھا۔میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہی انسان کی زندگی ہے؟ کیا یہی انسان کی زندگی کا چلن ہے؟ میرا من اس صدمہ سے بہت بوجھل تھا…… میرے گھر کا صحن بھی خالی خالی تھا۔ انسان کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے لگتا تھا کوئی دھیمی آواز میں کہہ رہا ہو۔۔۔ ”اِنسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں کا ہے۔ وہ پھول کی طرح نکلتا اور مرجھا جاتا ہے۔وہ سایہ کی طرح اُڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔“
…………٭٭٭…………
بوڑھا نیم اور ماسٹر جی
تحریر: پروفیسر عامرزرین /کراچی
گاؤں میں ہمارے گھر کے صحن میں نیم کا بوڑھا درخت تھا۔ جہاں کبھی دو کالی اور ایک بھوری گائے باندھی جاتی تھیں۔ لیکن بعد ازاں نہ جانے کیوں یہ سب جانور بیچ دیئے گئے۔ اب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم تمام بچہ لوگ ناشتے کے بعد اس درخت کے نیچے بارہ بجے تک پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے۔ ابّا جی سرکاری اسکو ل ٹیچر تھے۔ ہمارے آس پڑوس سے بھی چھوٹے بچے اپنے بستے سنبھالے ہماری کمپنی میں آجاتے۔ اگرچہ ابّا جی کے پاس ان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا وقت بھلا کہاں تھا؟چلو ہمیں تو تھوڑا بہت پڑھا دیتے اور باقی رہی سہی کسر ہماری باجیاں پور ا کردیتی تھیں۔ابّا جی گاؤں کے سرکاری اسکول میں سینئر ٹیچر تھے لہٰذا اسکول کے انتظامی اور دفتری امورمیں مصروف رہتے۔ کبھی کبھار دفتری کام سے شہر بھی جانا پڑتا تھا۔
گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول کا کام کرتے ہوئے مجھے بہت مزا آتا تھا۔اسی لئے میں انہماک اور شوق سے پڑھائی کے کام میں مصروف رہتا۔سورج جیسے سوا نیزے پر آتا نیم کے درخت کی چھاؤں اور گہری ہو جاتی تھی۔بلکل ایلسا کیزی کی نظم ”دی نیم ٹری“ کے مطابق کہ”نیم سُورج کی دھوپ کے آگے ڈھال بن جاتی ہے اور سارا دن دھوپ برداشت کرتی ہے۔“ابّا جی اگر اسکول سے جلدی آجاتے تو کمرے میں بیٹھ کر لکھائی پڑھائی کے کام میں لگ جاتے۔ اگر کسی دفتری کام سے شہر چلے جاتے تو ہمیں اس با ت کی پوری اُ مید ہوتی کہ ابّا جی شہر سے واپسی پر تربوز یا پھر آم لائیں گے۔اگر ابّا جی یہ پھل لے آتے تویہ دوپہر کے کھانے کے بعدکھائے جاتے۔ سادہ زمانہ تھا نہ سیل فون نہ واٹس ایپ، فیس بُک، ٹوئٹر، بوٹیم، انسٹا گرام جیسی قیمتی وقت کھا جانے والی قباحتیں۔گرمیوں کی ہر دوپہر کھانے کے بعد سونے کے لئے ہوتی تھی۔اکثر بچوں کی کہانیوں والی کتاب پڑھتے پڑھتے نیند آجاتی۔ ہمارے گھر کے پیچھے مستریوں کی دُکان تھی جو ساری دوپہر لکڑی یا لوہے کے کام میں مگن رہتے۔ اس لئے کبھی لکڑی کاٹنے یا لوہا کوٹنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں اور اب ہم اس شور سے مانوس ہوگئے تھے۔ میں شام کے اوقات میں فٹ بال کھیلنے کے لئے گراؤنڈ کی طرف نکل جاتا۔ رات میں ہلکا پھُلکا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ کر سوجاتا۔ فٹ بال جیسی تھکا دینے والے کھیل کی وجہ سے نیند بھی جلد آجاتی۔
ہمارا پڑوسی کہنے کو تو گاؤں کے بچوں کو انگریزی نثر اور گرائمر پڑھاتے تھے۔ اُن کا نام شفاعت تھا۔ہم اُنہیں انکل جی لیکن گاؤں کے بہت سے لوگ اور اُن کے شاگرد انکل جی کو ماسٹر جی کہتے تھے۔ سُنا تھا بلکہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ رائل برٹش آرمی میں آفس کلرک تھے اور جنگِ عظیم دوئم میں برما اور بنگال کے محاذوں پر تعینات بھی رہ چُکے تھے۔اُن کی زبانی بنگال کی ارضی اور نسوانی خوب صورتی اور جادو کے قصے سُن سُن کر مَیں محظوظ بھی ہوتا اور کبھی خوفزدہ بھی۔ ایک دفعہ انکل شفاعت جنگ ِ عظیم دوئم میں ڈھاکہ کے محاذ پر شہر کے مضافات میں امدادی چیزوں کی ترسیل میں مصروف تھے۔اُن کے ہمراہ دوسرے فوجی بھی تھے۔ ایک بستی میں اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک گھر میں وہ ایک انتہائی خوب صورت اور پُرکشش عورت کو دیکھ کر دم بخود ہوگئے تھے۔اُس عورت کا حُسن ناقابل ِ بیان تھا۔اُس کے بال اماوس کی رات کی طرح سیاہ اور سوانا کے جنگلوں کے طرح گھنے تھے۔اُس کے سیہ بال اُس کی ایڑیوں کو چھوتے تھے۔یہ قُدرتی دین اُس عورت کے نسوانی خدوخال کو بڑھاوا دیتی تھی۔اُس عورت کی ایک جھلک میں عجیب سی سحر انگیز کشش تھی۔ انکل شفاعت اور اُس کے ساتھی اس عورت کو دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئے تھے کہ جیسے وہ اس زمین کی مخلوق نہ ہو کوئی اپسراء ہو۔ابھی یہ قصہ جاری تھا کہ انکل شفاعت کے ٹیوشن والے بچے آگئے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک بہت دل چسپ بلاک بسٹر فلم میں انٹرول آگیا ہو۔ لیکن کچھ خبر نہیں تھی کہ منقطع ہونے والا سلسلہ کب دوبارہ سے جُڑے گا۔مجھے تجسس کی اتھاہ کیفیت میں چھوڑ کر انکل شفاعت بچوں کو فعل ماضی مکمل پڑھانا شروع کاچُکے تھے۔ لیکن میرے لئے اُن کی باتیں فعل ماضی جاری کی حیثیت رکھتی تھیں۔
ماسٹر جی دو دن مصروف رہے اُن سے مُلاقات نہ ہوسکی میرے سوچ اور خیال بنگال کے سحر انگیز حُسن میں اُلجھے رہے۔یہ اسّی کی دہائی کا دور تھا۔ابھی گلو بل لائزیشن کے ہنگام ڈیجیٹل عہد کا آغاز نہیں ہوا تھا۔بلکہ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کی منازل سے بہت پیچھے اپنے بام ِ عروج کی طرف خراما ں خراماں ریس میں جیتنے والے سُست رو کچھوے کی طرح محو سفر تھی۔ اس لئے ممکن نہیں تھا کہ میں بنگال کے علاقائی رہن سہن اور روایات کے بارے میں معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کر پاتا۔اُس دوَر تک زبانی قصہ گوئی اور داستان سُنانے کی روایت اپنی اہمیت اور دل چسپی کے ساتھ جوان تھی۔لیکن شاید اب لوگو ں کے پاس اپنے ماحول اور اس میں موجود سانس لینے والے دوسرے انسانوں کے لئے وقت نہیں ہے۔تو پھر داستان گوئی کو کون خاطر میں لاتا ہے، اسی لئے سماجی رابطوں کو جوڑنے والی ایسی روایات متروک ہوچُکی ہیں۔
ہر رات ماسٹر جی کے پاس وقت ہوتا لیکن میں شام کی تھکا دینے والی مصروفیات کی وجہ سے جلد سوجاتا۔ ماسٹر جی کے پاس ایمبسیڈر کمپنی کا ایک ٹرانسسٹر ریڈیو تھا جو کہ فراغت کے اوقات میں اُن کا وفادار ساتھی تھا۔جنگِ عظیم کے ختم ہونے کے بعد آج تقریباً 35 برس کے بعد بھی ماسٹر جی اسی شوق اور فکر کے ساتھ بی بی سی سے سیربین بلاناغہ سُنتے کہ جیسے اس بُلیٹن میں جنگِ عظیم کے دوران کی تازہ صورتِ حال پر اپ ڈیٹ دیا جا ئے گا۔جرمنی کے پسپاہونے اور اتحادیوں کی مختلف مقبوضہ مُلکوں کی آزادی کے لئے پیش قدمی کی خبریں دی جائیں گی۔ حالاتِ حاضرہ کی خبریں سُن کر جب جب موقع ملتا وہ ہر ملنے جُلنے والے کے ساتھ یہ خبریں شئیر کرتے اور اس پر تبصرہ بھی فرماتے تھے۔ اگرچہ اُس دور میں شاید جھوٹ اور منافقت معاشرتی روایات میں اتنی سرایت نہ کرگئے تھے کہ میڈیا نیوز ڈپلو میسی پر انحصار کرتے۔ کہا جاسکتا ہے کہ کافی حد تک ایک شفاف اور مخلصانہ طرزِ زندگی تھا۔ اگرچہ عالمی سطح پر یہ سرد جنگ کا دور تھا اور مُلکی سطح پرتیسری مارشل لاء کا زمانہ تھا۔ تمام ابلاغ پر ضیائی مارشل لاء کا تسلط تھا۔ قومی ٹی وی کی کوئی خبر یا پروگرام سنسر شپ کے مراحل سے گذرے بغیر پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابّا جی اور ماسٹر جی مُلکی میڈیا کی خبروں پہ بی بی سی کی خبروں کو زیادہ معتبر مانتے اور ترجیح دیتے تھے۔
ماسٹر جی بزرگ تھے 70 سے زائد بہاریں دیکھ چُکے تھے۔برٹش رائل آرمی میں ہوتے ہوئے وہ اُس عظیم عالمی واقعہ کے چشم دید گواہ بھی تھے جب 1945 ء میں دوسری جنگِ عظیم دوران امریکی سامراج نے نامور سائنسدان البرٹ آئن سٹائن کے فارمولا کی بنیاد پر ایٹم بم بناکر جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگا سا پر اس مہلک ہتھیار کا عملی تجربہ کیا بلکل ویسے ہی جیسے ناگہانی کورونا ویکسین بغیر ٹرائل کے دُنیا بھر میں بالجبر لگائی جارہی ہے۔۔ اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زائد بے گناہ انسان ایٹم بم ٹرائل کا لقمہء اجل بن گئے تھے۔ ہر حساس انسان کی طرح یقینا ماسٹر جی کے لئے بھی یہ المیہ ناقابلِ فراموش تھا۔
ان تمام تلخ وشیریں ماضی کی یادوں کے باوجود ماسٹر جی بڑھاپے میں بھی ایک پُر اثر اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔جہاں ماسٹر جی بنگال کے حُسن سے متاثر ہوئے نہیں رہ سکے ہوں گے یقیناوہیں لمبے گھنے بالوں والی اپسراء کی دھڑکنیں ماسٹر جی کو دیکھ کر ضرور تیز ہوئی ہوں گی۔
میں نے جب ہوش سنبھالا تو ماسٹر جی کو تنہا ہی دیکھا۔ ہمارے گھر میں کبھی کبھار یہ بات سُننے میں آتی تھی کہ ان کی شریکِ حیات گھریلو انارکی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔مضبوط ارادوں والے فوجی کی دلیری، بہادری اور اناء ان کے جذبات اور خاندانی محبت پر غالب رہے۔نہ کبھی انہوں نے اپنی شریکِ حیات کو لانے کی کوشش کی اور نہ کبھی اُس بھاگوان نے گھر کی طرف لوٹ آنے ارادہ کیا۔سُنا تھا کہ کچھ عرصہ تک ماسٹر جی سرِ شام بس اسٹاپ پر جاکر ناراض لوگوں کی واپسی کا انتظار کئے کرتے تھے اور پھر مایوس ہوکر یقینا بھاری دل کے ساتھ لوٹ آتے۔
ماسٹر جی ہر رات آل انڈیا ریڈیو سے فرمائشی فلمی گانوں سے لُطف اندوز ہوتے۔خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں رات جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا تو اُن کے ٹرانسسٹر سیٹ سے انڈین فلمی گانوں کی آواز دُور دُور تک سُنی جا سکتی تھی۔ چند ایک گانے تو جیسے ماسٹر جی کے دل کی آواز تھے۔کیونکہ میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا محسوس کر سکتا تھا کہ جب جب وہ مخصوص گانے نشر ہوتے ماسٹر جی ریڈیو کی آواز تھوڑی اور بڑھا دیتے تھے۔ شاید وہ اپنے محسوسات اور کسی کی جُدائی میں اپنے ماحول کی ہر چیز کو شریک کرلینا چاہتے ہوں۔ایک گانے کے بول مجھے آج بھی یاد ہیں، جو کچھ ایسے تھے، ”……تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے ہائے…… ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے“۔ رات کی خاموشی میں یہ گانا واقعی کیا سماں باندھتا تھا کہ بہت سے ہجر اور جُدائی کے ماروں کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔اسی طرح چند اور انڈین فلمی ٹریک ماسٹر جی کے پسندیدہ تھے خاص کر جن میں انتظار اور انتظار میں محبت اوریاد کے موضوع پر شاعری ہوتی اور سونے پہ سہاگہ سادہ اور پُر تاثیر گلوکاروں کی آواز اور موسیقی عجیب سماں باندھتی تھی۔ وہ انتہائی سادہ زمانہ تھا، لوگ بھی سادہ تھے۔ ہم بھی اُس وقت تک قلبی وارداتوں کے اثرات سے آزاد تھے۔لیکن آج اس دور اور عمر کے اس پُختہ حصے میں ماسٹرجی کی قلبی کیفیت اور جُدائی کے دُکھوں کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔
چند سالوں میں جیسے جیسے میں تعلیم کے درجات میں آگے بڑھتا گیا، میرے لئے گاؤں میں رہ کر مزید تعلیم کا حصول ناممکن نظر آنے لگا تھا۔اِن مُشکلات کے پیشِ نظر بڑے بھائی جان نے مجھے اپنے پاس شہر میں بُلا لیا۔ پھریہ وقت آیا کہ گاؤں سے دور ہوئے اور پردیس نے اپنے پھیلے بازؤں میں پناہ دی۔مَیں نے خُود کو شہر کے تیز، چالاک، ہوشیار، کہیں مخلص تو کہیں خود غر ض اور لالچی لوگوں میں پایا۔ گاؤں کے سادہ اور سیدھے سادھے لوگ، اُن کی باتیں اور یادیں سب دُھندلی پڑنے لگیں۔ کالج میں داخلہ لیا۔ نیا ماحول نئے دوست،زندگی میں نئے چیلنج اور ایسے ہی دن بدن اور ماہ بہ ماہ گاؤں کے لوگوں سے دُوری اور لاتعلقی بڑھتی گئی۔لیکن شہر میں شہر کے لوگوں میں اپنی پہچان ضرور قائم رکھی کہ میرا تعلق گاؤں سے ہے۔ترقی کی منازل کی طرف گامزن گاؤں سے سماجی رابطے جیسے دُھندلا ساگئے۔اِن راستوں پہ جیسے گھاس اُگنے لگی۔خط و کتابت کا سلسلہ تھا تو صرف اپنے گھر والوں سے۔ اُس وقت گاؤں میں ٹیلی فون نام چیز کا وجود تک نہ تھا۔کالج سے فارغ ہوا تو گھر والوں کے اسرار پر گاؤں جانے کا پروگرام بنایا۔خیر اپنی جنم بھوم کی طرف محوِ سفر ہوا تو گاؤں کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔مجھے گرمیوں کی چُھٹیوں کے دن یاد آرہے تھے جب بوڑھے نیم کے درخت کی چھاؤں میں ہم سب بہن بھائی اپنے اسکول کا کام کیا کرتے تھے۔آس
پڑوس کے بچوں کے چہرے بھی ایک ایک کرکے میری نظر میں آئے جو ہر صبح اپنے بستوں اور کتابوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھائی میں شریک ہوجاتے تھے۔ یادوں کی بیاض کے دفتر میں ماسٹر جی کا باب بھی کُھلا۔ وہی ہر شام بی بی سی کے نیوزبُلیٹن،وہی رات گئے آل انڈیا ریڈیو پر فرمائشی فلمی گانوں کا پروگرام، جس کے کچھ سحر انگیز گانے مجھے لوری دے کے سُلا دیتے تھے اور دوسری طرف ماسٹر جی کی جُدائی کے زخموں کوہرا کردیتے تھے۔
میں بعد از دوپہر گھر پہنچا۔سفر کی تھکاوٹ بھی تھی اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک بے رونقی اور ویرانی کا احساس ہوا۔صحن بھی خالی خالی اور کُشادہ لگا۔ نیم کا درخت اپنی جگہ موجود نہ تھابلکہ اب وہاں شیشم کے دودرخت جنہیں میں نے کچھ برس پہلے بہت چھوٹے چھوٹے دیکھا تھا لیکن اب وہ اپنی جڑوں کے ذریعے زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرچکے تھے۔میرے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ ایک شام تیز اور طوفانی آندھی نے نیم کے درخت کو جڑ سے اُکھاڑ دیا۔آخرِ کار اُسے یہاں سے ہٹانا ہی پڑا۔
اس بار میرے گھر کے پڑوس میں ایک وحشت انگیز سکوت تھا، ایک خاموشی تھی۔میرے استفسار پہ کہ ماسٹر جی کا ریڈیو آج کیوں خاموش ہے؟ میرے ابا جی نے بتایا کہ تمہیں خط میں بتایا تو تھا کہ چند ماہ قبل ماسٹرجی حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے عدم سدھار گئے۔شہر کی مصروف زندگی اور تعلیمی سرگرمیوں کے باعث شاید میں اس خبر پر توجہ نہ دے سکا تھا۔لیکن مجھے اس وقت یہ خبرسُن کرانتہائی صدمہ ہوا۔ماسٹر جی کا آخری وقت کچھ اس طور اٹل اور مختصر تھا کہ اُنہیں ہسپتال لے جانے کہ مہلت بھی نہ مل سکی۔وہ شام بہت عجیب تھی۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔لیکن نہ تو مارک ٹلی کی خبروں کا بُلیٹن، نہ ہی فرمائشی فلمی گانوں کی آواز،نہ ہی نیم کے پتوں کی سرسراہٹ اور نہ ہی نیم کے بُورکی مسحورکُن خُوشبو تھی۔ مجھے ماسٹر جی اور نیم کے بوڑھے درخت سے بچھڑنے کا انتہائی افسوس تھا۔میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہی انسان کی زندگی ہے؟ کیا یہی انسان کی زندگی کا چلن ہے؟ میرا من اس صدمہ سے بہت بوجھل تھا…… میرے گھر کا صحن بھی خالی خالی تھا۔ انسان کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے لگتا تھا کوئی دھیمی آواز میں کہہ رہا ہو۔۔۔ ”اِنسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں کا ہے۔ وہ پھول کی طرح نکلتا اور مرجھا جاتا ہے۔وہ سایہ کی طرح اُڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔“
…………٭٭٭…………