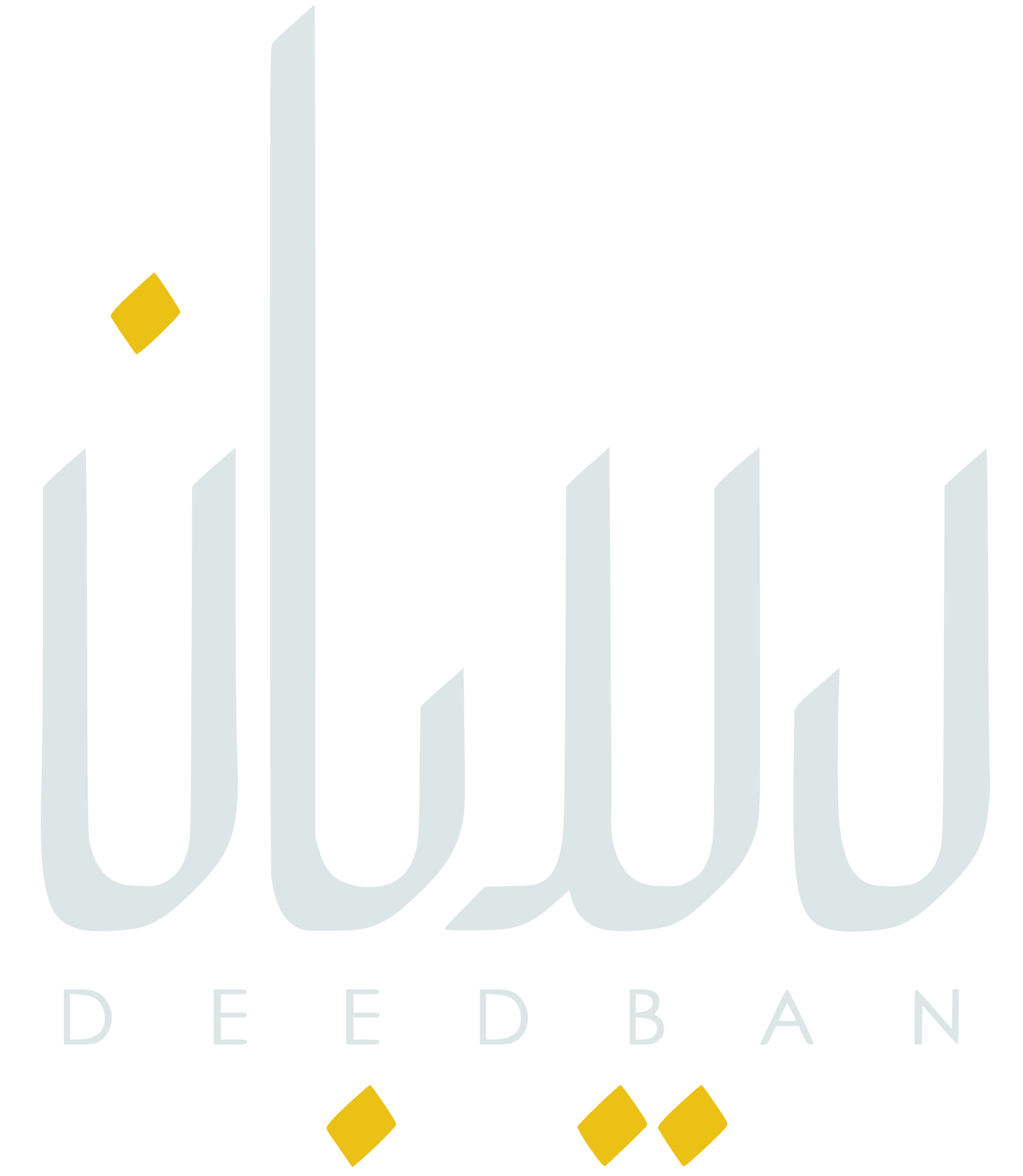پسِ غبار سفر
پسِ غبار سفر
Mar 15, 2018

دیدبان شمارہ ۔۶
پسِ غبار سفر
خالد قیوم تنولی
(چوتھی قسط)
باب - 8
’’بزمِ اہلِ فکر‘‘ کی پہلی باقاعدہ تقریب کا انعقاد ہوا لیکن میں دانستہ شامل نہ ہُوا۔ آمنہ بیمار تھی اور اس کی بیماری نے مجھے ان گنت وسوسوں سے دو چار کر دیا تھا ۔ اُسے دھیما دھیما بخار رہنے لگا تھا۔ حکیم نشتر انصاری کی مُجرّب دوائیں بھی رائیگاں جا رہی تھیں ۔ ایک جانکاہ تشویش مجھے زمین میں زندہ دھنسائے جاتی تھی۔ ندیا کے پار گھمبیر اسرار والے جنگل کی دوسری جانب ایک بڑے قصبے میں کئی نامی گرامی شفا خانے تھے اور ماہر معالج بھی مگر آمنہ نہ مانتی تھی۔ میرے بار بار کے اصرار کے باوجود وہ خود اختیار لا پرواہی سے مسکرانے لگتی اور یوں ظاہر کرتی گویا دنیا کا کوئی بھی مرض اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ مگر بہ خدا ایسا نہیں تھا۔ میں چوری چھُپے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور تمام علامتیں اور تأثرات بھانپ رہا تھا جنہیں وہ مجھ سے چھپانے کی حتی الوسعیٰ کوشش کرتی۔ میں بہ خوبی جان رہا تھا کہ ہمارے لیے اس کی توجہات میں دن بہ دن کمی واقع ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا گریز اس نے خود کو لاحق کر لیا تھا ۔۔۔ اور یہ بہت اندو ہناک تغیر تھا جو ہمیں دھیرے دھیرے گھیرتا چلا جا رہا تھا ۔ وہ ہمیں پیش آمدہ حقائق اور حالات سے نپٹنے کے لیے تیارکر رہی تھی ۔ ایک مضروب بے کسی ، زخم زخم سی خاموشی، بے نیازی اورفراریت ہمارے درمیان جگہ بنانے کوپَر تولنے لگیں ۔ ردِ عمل میں وہ ساری پس انداز قوتیں اچانک جاگ اٹھیں جو کڑے وقت کے انتظار میں سوئی ہوئی تھیں۔ دو وجود نظر انداز ہو رہے تھے۔
اندیشے روح کے روزنوں سے اندروجود میں جھانکنے لگے تھے۔ ایک مثالی محبت پر وہ غم طاری ہو رہا تھا جس کی شرح نا ممکن ہے۔ وہ تمام علامتیں جو میں نے بھانپ رکھی تھیں انہیں میں نے از سرِ نوَ ازبر کیا اور آمنہ کو بتائے بغیر خود ہی معالجین سے مشاورت کی غرض سے صبح سویرے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔نورو ملاح کی ناؤ دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی ۔ وہ ایک مائل بہ حدت، غنائیہ اور اداس دن تھا۔ ناگاہ میری نظر رواں پانی پر پڑی تو دائمی خوف نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ میں نے گھبراکر نہایت روشن، اجلے اور نیلے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نورو ملاح کے بوڑھے مشقتی بازو ایک مخصوص ردِھم سے چَپّو چلا رہے تھے اور شڑاپ شڑاپ کی عمومی آواز کے سوا کوئی آواز نہ تھی ۔ ناؤ دوسرے کنارے سے جا لگی تو نُورو نے کھنکار کر بلغم کا غلفہ پُر شور انداز سے تھوکا اور دونوں بازوؤں کو ہوائی چکی کے پنکھے کی مانند گھمانے لگا۔ میں نے کُرتے کی بغلی جیب سے کچھ روپے نکالے اور اس کی جانب بڑھائے ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا پھر ایک چھچلتی ہوئی سیراب سے نظر میری مٹھی کے روپوں پرڈال کر رُخ پھیر لیا: ’’کیا تُو نہیں جانتا؟‘‘’’کیا۔۔۔ میں کیا۔۔۔ میں سمجھا نہیں بابا‘‘’’یہی کہ میں کرایہ نہیں لیا کرتا‘‘’’کیوں ؟‘‘’’کیا تُو نہیں جانتا؟‘‘’’نہیں ‘‘’’پچہتر سال ہونے کو آئے ۔ دس سال کا تھا جب پتوا رپہلی بار تھامے تھے۔ آج تک کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا۔۔۔ مرشد کا بس یہی حکم تھا۔ آج تک حکم عدولی نہیں کی میں نے‘‘’’اچھا ۔۔۔مجھے واقعی معلوم نہ تھا‘‘ میں نے تعجب سے خالی لہجے میں کہا کیونکہ ایک مدت سے مَیں حیرتوں کا عادی ہو گیا تھا۔ ’’کب تک واپسی ہو گی؟‘‘’’شام سے پہلے‘‘’’میں انتظار کروں گا‘‘’’شکریہ‘‘’’خدا کی امان‘‘اس کنارے پر سر کنڈوں کے جھنڈ تھے جن میں جا بہ جا جنگلی سؤ روں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ میری لاٹھی کی ٹھک ٹھک سے ایک ریوڑ بدک کر بھاگا۔ میں نے چند پتھر اُن کی طرف پھینکے اور اونچا اونچا انہیں بُرا بھلا کہا۔ سرکنڈوں کے جھنڈ سے باہر نکلتے ہی رستہ جنگل میں داخل ہو رہا تھا اور جنگل مختلف آوازوں سے بھرا پڑا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور درختوں میں سر ٹکراتی ہَوا کی سرسراہٹ تھی ۔ خود رو انگوروں کی بیلیں تھیں ۔ سورج کی روشنی کم کم پہنچ رہی تھی ۔ بہتے جھرنوں کی مانوس چاپ تھی جیسے سانپ رینگ رہے ہوں ۔ میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہُوا ہر شے کو اپنی یاداشت کی زنبیل میں سنبھالتا چلتا رہا۔ کہیں نمی کی بہ دولت پتھروں پر سبز کائی نے اپنی حاکمیت جما رکھی تھی اور کہیں وہ پودے بھی تھے جن کے متعلق برسوں قبل نصاب میں پڑھا تھا۔ مجھے ان پودوں کے روایتی نام معلوم نہ تھے۔ سانپ کی جلد کے چھلکوں کی طرح کے ما رکنشیا ،چاکلیٹی رنگ کے فلجے نیلا اور کھٹ مٹھے پتوں والے ایڈی انٹم اور شیر خوار بچے کے سر کے ملائم پشم جیسے گریمنی کے لچھے تھے۔
ایک مُنے سے جھرنے کے نیچے رُک کرمَیں جب چُلو بھر بھر کر تازہ، یخ اور شیریں پانی پینے لگا تو اچانک وہی برسوں کی جانی پہچانی ، پُر سوز اور مدھر، بانسری پر چھڑے کسی گیت کی کبھی مدھم اور کبھی بلند ہوتی ہوئی دھن سنائی دینے لگی ۔ کس سمت سے آرہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ اندازہ لگانا محال تھا لیکن اتنا ضرورہُوا کہ مجھ میں خاطر خواہ تونائی پیدا ہونے لگی ۔ گیت کا ایک بند پورا ہوا۔ وقفہ آیا۔ پھر ایک نسوانی ہنسی کی گونج سارے میں پھیل گئی ۔ جیسے لہروں کا گرداب ساری سطح آب کو اپنی اثریت میں لے لیتا ہے۔ اس ہنسی کے تعاقب میں کوئی قہقہہ تھا۔ کچھ دیر ماحول میں ہلچل سی رہی۔ اگلے ہی لمحے سناٹا تھا۔ پھر اس سناٹے نے ایک سوال کو میری سماعتوں کی جانب اُچھال دیا۔ ’’تم کہاں چلے گئے تھے؟‘‘جواب میں خاموشی تھی۔’’اب تو کہیں نہیں جاؤ گے نا؟‘‘وہی خاموشی۔’’بولو گے بھی یا مسکراتے ہی رہو گے؟‘‘ہنوز خاموشی۔’’مجھے یوں مت دیکھو ۔ لاج آتی ہے‘‘اب ایک نمایاں اور رفیع تر قہقہہ گونجا جس کے پسِ منظر میں مترنم ہنسی کی بازگشت بہہ رہی تھی ۔ میری آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو بے ارادہ ہنستے ہنستے اُمڈتے مجھے محسوس ہوئے ۔ ہر وہ بات جس کا ناطہ گداز اور حساسیت سے ہو، میرے آنسوؤں کولاچار اور بے اختیار کر دیتا تھا۔ سو اُس وقت وہی ہُوا جس کی مجھے امید تھی۔میرے قدم اٹھنے لگے۔’’ادھرمیری طرف دیکھو۔۔۔۔‘‘ یہ مردانہ التماس تھی۔’’کیوں ؟۔۔۔۔کیوں دیکھوں ؟‘‘’’میرے چند سوال تمہاری آنکھوں میں گِر گئے ہیں ‘‘’’سوال نہیں یہ میرے اپنے واہمے ہیں ‘‘میں ان باتوں کے حصار کے قریب ہو رہا تھا۔ تنگ، پتھریلی اور ناہموار رہ گزر پر یوں چلنے لگا جیسے چھپکلی دیوار پر رینگ رہی ہو۔ ایک مختصر سا ہری بھری گھاس کا تختہ میرے سامنے تھا جس پر دو انسانی وجود آمنے سامنے بیٹھے دکھائی دیے۔ مرد جس کے گہرے سانولے چہرے پر چیچک کے بے شمار بد نما داغ تھے۔ کُبڑا اور بد وضع، گلے میں بہت سے مالائیں، کانوں میں بالے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، پیروں میں کڑے، سیاہ لباس اور وہ بھی پیوند زدہ۔ قریب ہی ایک تھیلا ، کشکول اور لاٹھی دھری تھی۔ پہلی نظر میں وہ بد صورت غمگین اور مضحکہ خیز لگا لیکن پھر پُر کشش ، اپنائیت بھرا،پُر کیف ، رنگ رنگیلا اور متوکل محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی بانسری کو اپنے سیاہ سکڑے ہوئے ہونٹوں سے چپکائے بیٹھا تھا اور چھوٹی چھوٹی چند ھیائی ہوئی آنکھیں بند تھیں ۔ اور عورت جس کی ہنسی کی آواز میں ملفوف کرب کی تاثیر کو پا کر میرے آنسو متوحش گھوڑوں کی طرح آنکھوں سے کود پڑے تھے درحقیقت نہایت خوش رُو اور نوخیز دوشیزہ تھی ۔ اُس سمے اس کی ہنسی کسی گہرے خیال کے نیچے دب چکی ہو گی کہ وہ اپنے زانوؤں پر بائیں ہاتھ کی کھلی ہتھیلی پر داہنے بازو کی کہنی جمائے اوردائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنا آدھا چہرہ چھپائے چُپ سے ہمکنا رتھی۔ پلکوں کی جھالریں آنکھوں پر پڑی تھیں اور اس کی سیاہ لامبی زلفیں پشت سے زمین تک یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے آبشار گر رہی ہو اور پانی دُور تک بہہ رہا ہو۔ اس کا پیر ہن اس کی بے پناہ امارت کا غماز تھا۔ رنگت ایسی کہ گویا ہمیشہ دھوپ سے کنارا رہا ہو۔ وہ معمورِ شکوہ جسے صدیوں آنکھ جھپکے بنا با آسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک بہت واشگاف تضاد کی زندہ تصویر میرے سامنے تھی۔ ایسا نمایاں فرق میری آنکھوں میں رڑکنے لگا جو خواب اور سراب کے درمیان معلق رہتا ہے۔’’تم نے پوچھا کہ میں کہاں چلا گیا تھا ۔
تمہاری آنکھ کے سوالیہ زاویے میری زنبیل پر منعکس ہوتے ہیں اور میرے کشکول میں تمہارے تحیّر کے سکے کھنکھناتے ہیں ۔ تمہارا کہنا ہے کہ تمہیں رونا نہیں آتا۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ کوئی عورت بغیر اشکوں کے جی سکتی ہے ۔ تم نہ بتاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ مدتوں کی بے خودی نے مجھے اس خوبی کا حامل بنا دیا جو کسی بھی سینے کی اتھاہ زنبیل میں ہر غم کی نمی کو پرکھ لیتا ہے ۔ تو نہیں جانتی کہ میں کیوں دریوزہ گر بنا؟۔۔۔ کن جذبوں کا مجھے قحط لاحق ہے ۔ کیا تُو نہیں جانتی؟ تو وہ غنی ہے جو اگر دستِ مروّت بھی بڑھائے تو رلکِ زاروں میں نخلستان اُمڈ آئیں ۔
میری زنبیل میں کیا ہے ۔ کیا تو نہیں جانتی؟ ۔۔۔ جس میں نہ جانے کن زمانوں کی آرزوئیں پڑی ہیں ۔ کتنی حسرتوں کے جنازے بھرے ہیں ۔ کس قدر طلسم آثار آہوں کے پُرزے مقید ہیں ۔ میں کہاں جا سکتا ہوں ۔ محبت کی سطروں میں چھپا مفہوم بھی کہیں جا سکتا ہے ۔ اشکوں کی قیادت کرنے والا جذبہ بھی کبھی کھو سکتا ہے ۔ میں وہ گڈریا جو اپنی سوچوں کو طلوعِ سحر سے غروبِ شام تک دل کی بے کنار چراگاہوں میں چراتا پھرتا ہوں ۔ ۔۔۔ سوچو اگرگڈریا کہیں چلا جائے تو سوچوں کی رکھوالی کون کرے گا؟۔۔ میں سو بھی جاؤں تو یہ سوچیں میرے گرد بیٹھی میرے سانس سونگھتی رہتی ہیں ۔
ہائے ۔۔۔۔ اے ستم پسند محبت!
تیرا شکریہ۔۔۔ جس نے عین جوانی میں مجھے لاٹھی ٹیکنے کا فن سکھا دیا۔۔۔‘‘میرایوں ہونقوں کی طرح ان دونوں کو تکنا مناسب نہ تھا مگر ایک مجبور دلچسی نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس بے پناہ وابستگی اور جان نثاری کی زندہ تصویر سے اگر چہ میں باہر تھا تاہم اپنا وجود اضافی محسوس ہو رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی وقت جاتا ہے جب ان دونوں کی آنکھیں کھلیں گی اور میرا ہونا ایک ناگوارسوال میں ڈھل جائے گا اور وہ دو نایاب ترین پیکر خوشنما پرندوں کی طرح اُڑ جائیں گے اور پھر میں اپنی زندگی میں ویسا منظر کبھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ مرد خاموش ہُوا تو نو خیز دوشیزہ بولی:’’میں اپنی مٹھی کی ریکھاؤں میں تمہیں کبھی جو موہوم سا ہوتا دیکھوں پھر پوچھنا تو پڑتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ گزرے ہوئے لمحات کی یادیں بُجھے ہوئے دئیے اٹھائے ماتم کر تی نظر کے قلعے کے سامنے آبیٹھیں تو دل بے پناہ وسوسوں کی آماجگاہ ہو ہی جاتا ہے ۔ ۔۔۔ پھر میں کیوں نہ پوچھوں کہ تم کہاں چلے جاتے ہو۔ میری بیاضِ روزو شب کے بکھرے اوراق پر تمہارے قدموں کے دستخط ثبت ہیں ۔۔۔ اگر کوئی ورق ذرا سی دیر کے لیے خیال سے اوجھل ہوجائے تو کیا تشویش نہیں ہوا کرتی۔ میں اپنے واہموں سے خوف زدہ ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں کیوں پوچھتی ہوں۔ تم نے میری آنکھوں کو جن خوابوں کا عادی بنا دیا وہ مجھے رونے نہیں دیتے ۔۔۔
میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ آنسوؤں اور محرومی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔۔۔ اور یہ تعلق مجھے دو چار نہیں ہوا۔۔ مجھے اندیشوں کے اہرام میں مقیدہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگے تو روح وجود سے باہر آکر چھاتی پیٹنے لگتی ہے۔ میرے یقین کی دیوار کو آزمائش کے ناخنوں سے مت کریدو۔ ذرا بتاؤ تو شہد کی مکھیوں کو میری روح کی خبر کس نے دی ؟ میرے وجود میں خوشبو نے کیوں ڈیرے ڈال دئیے ؟ ۔ تتلیاں میری ذات کے گرد کیوں منڈلانے لگیں ۔ روشنی کے جگنو کیوں مجھے تاکنے آتے ہیں ۔ مجھے اب کیوں اس بحران کے سپرد کرنے چلے ہو جس میں سناٹے ہی سناٹے ہوتے ہیں ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس صراط مستقیم سے کنارا کرلوں جو سرا سر ’’تُو‘‘ سے ’’تُو‘‘تک لامحدود ہے۔ کیا تم سہہ سکو گے کہ میں کسی ایسی سمت کا رُخ کروں جو ہمارے مشترکہ تجربات میں نہ آئی ہو۔۔۔ مجھے میری ’’مَیں‘‘ کا سایہ بھی کب کا چھوڑ چکا۔ اب میرا اپنا کوئی انداز نہیں رہا۔ کوئی روپ نہیں رہا۔ مجھے اپنی عادت نہیں رہی۔ خود پہ اختیار نہیں رہا۔نیند میں چلتے ہوئے فرد کی راہ کا انتخاب کون کرتاہے؟۔۔۔۔ بتاؤ؟۔۔۔ مجھ سے پہلے اپنی آنکھیں کھولو۔۔۔ دیکھو! میری ذات کا آئینہ میری ہست سے انکاری ہے۔ اس میں اب میرا عکس ہی نہیں بنتا‘‘ جانے کب تک میں ان دونوں کے اسلوبِ گفتگو میں کھویا رہا جو اپنے آغاز سے منطقی و معنوی تسلسل اور ایک واضح ربط سے معمور تھی۔ ان کی تمثالیں اور کنائے شعری لطافتوں سے ہم آہنگ تھیں اور اندازِ اظہار کسی ایک کیفیتِ خیال سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے باہمی ربط میں مجھے تحیّر، تعقل، حیرت، تصادم ، تنبیہ اور تہدید کے بے شمار گوشے پنہاں دکھائی دیئے جو نہایت زیریں دلچسپی اور وفورکے بنا اُبھارے نہیں جاسکتے اور ان سے اُبھرنے والی صداقتیں ہمہ وقت زندگی کرنے کے کام آتی ہیں ،بڑی علامتوں کے ساتھ بیان ہو رہی تھیں ۔ میں نے قدم آگے کی سمت بڑھا دئیے اور اُن دونوں نے بہ یک وقت مجھے دیکھا اور مسکرائے مگر کوئی بات نہ کی ۔ وہ فقط ایک مانوس محویت کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں اپنی پیٹھ پر ان کی گداز، کریم اور مہربان نظروں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دوسری طرف کی ڈھلوان اترنے لگا اور دل پر اترتی اس منظر کی لطیف فضیلت سے مسرور اور پھر کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکنے کے تصور سے مغموم بھی ہوتا رہا۔ ڈھلوان کے حتمی موڑ پرقصبے کا قبرستان دُور تک پھیلا تھا۔ پختہ و نیم پختہ قبروں کا بے تحاشا ہجوم جس کے حُسن میں مختلف قامتوں اور رنگوں کے کتبے اضافہ کر رہے تھے۔میں نے فاتحہ پڑھ کر اپنے گمنام ہم نفسوں کی روحوں کو نذرِ ثوا ب کی اور مزید آگے بڑھنے سے قبل راہ گزر کنارے بنے ایک حوض سے پانی پیا۔گورستان کے عین درمیان پہنچ کر میں نے چاہا کہ بابُ العلم حضرت علیؓ کے وہ مصرعے دہراؤں جب انہوں نے جنگِ صفین سے واپسی پر دارلخلافے کی طرف ایک قبرستان سے گزرتے وقت فرمائے تھے:’’کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟اے وحشت زدہ گھروندوں اور اُجڑے مکانوں کے مکینو! میرا سلام قبول ہواے بے کسی کے مارو!اے خاک نشینو!تم جو تیز قدم ہم سے آگے نکل گئےاور ہم بھی بس آیا ہی چاہتے ہیں تمہارے قدموں کے نشان نشانِ راہ ہیں سنو! جو گھر بنائے تھے تم نےان میں کوئی اور بس رہا ہےجو بیویاں چھوڑی تھیں ان سے غیروں نے نکاح کر لیےاور وہ مال ہلکان ہوئے تم جس کے سببدوسروں نے کھالیا ہےیہ تو تھی ہمارے ہاں کی خبر کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟‘‘میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی پُرنم آنکھیں پونچھیں اور موت کو یاد کرتا ہُوا گورستان سے باہر آگیا۔ سامنے پکی سڑک کے پار جدید شفاخانوں کی عمارتیں کھڑی تھیں ۔
----------
باب -۹
ہماری لاکھ منتوں سماجتوں کے باوجودآمنہ نہ مانی معالجین اور طبیبوں کی وہ ساری دوائیں بھی اکارت گئیں جو بڑے دعووں کے ساتھ مجھے سونپی گئی تھیں کہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے مجرّب ہیں ۔ ہمارے بے شمار دفعہ کے اصرار کے باوجود آمنہ نے بتا کر ہی نہ دیا کہ اسے کون سا روگ لاحق تھا۔ جانے کس نا قابلِ گفت کیفیت سے نڈھال رہنے لگی۔ اس کا کروفر خدادادتھا مگر طبیعت کو جکڑتی ہوئی کسل مندی سے منہدم ہُواجاتا تھا۔ رُخساروں کی تابناکی مدھم پڑتی جاتی تھی۔ اُس کا روشن جسم گیلی لکڑی ہُوا جاتا تھا۔ لب پھیکے اور ان پر مستقل فروکش رہنے والی خفیف سی مسکان بے نام سی غفلت سے مغلوب رہنے لگی ۔اس کا بہت غنی دل بے اعتنائی کی کسک کی طرف مائل تھا۔ جن آنکھوں میں اطمینان کی چکا چوند کے میلے لگے رہتے اب یوں اُجڑتی جا رہی تھیں جیسے تند آندھی میں خیمے اُکھڑ کر اُڑ جاتے ہیں ۔۔۔ مگر وہ اعتراف سے گریزاں تھی اور ادھر ہم باپ بیٹی کے دلوں پر شبہات اور واہموں کے اژدھے کنڈلی مارے بیٹھے تھے ۔ ذرا سی خوش گمانی سر اٹھاتی تو اژدھے پھنکارنے لگتے۔ ہم تینوں بے تقصیر مجرموں کی طرح نظریں ملانے سے تغافل برتنے لگے تھے۔ بارہا میں نے دیکھا کہ مریم کسی خوفناک سناٹے سے الجھی ہُوئی خاموش آنسوؤں سے روئے جاتی ہے ۔میں نے پکارا تو بولی نہیں ۔ بس سرکی موہوم سی جنبش سے جواب دیا اور میں پلکوں پر آنسو روکے ادھر اُدھر گھومتا پھرا۔ معمولاتِ زیست جوں کے توں رواں تھے۔ کوئی خلل پیدا نہ ہو رہا تھا لیکن وقت حشرات الارض کی طرح رینگ رہا تھا ۔ مجموعی حیات بیمار کی رات ہو کے رہ گئی ۔ مسکراہٹ ہو یا نظر اپنے اپنے منبع سے بے خبر ہو گیءں ۔ جینے کی وہ ترتیب اور تہذیب جو آپ کے فیض کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوئی، زینہ زینہ بڑھتی خوش اسلوب اور خوش وضع ہوئی ، اس میں کوئی ایسا سقم پیدا ہوا جو ہماری گرفت میں نہ آرہا تھا۔ عجیب تغیر تھا۔ایسی ہی نا مطمئن، سوگوار اور بے قرار صبح صادق کو میں سو کر اٹھا تو آمنہ اپنے بستر میں نہ تھی ۔ صاف سلجھے اور بے شکن بستر کے ساتھ طرفہ میز پر ایک سبز کاغذ دھرا تھا۔ میں متجسس ہوا اور مضمحل وجود کو گھسیٹتا ہوا میز تک پہنچا۔ لیمپ کی روشنی میں میں نے وہ تحریر دیکھی جس سے میں اتنا ہی مانوس تھا جتنا کہ اپنے سانسوں سے ۔ آیتِ کریمہ درج تھی:’’ہم لوگوں کے درمیان ایام کو پھراتے ہی۔‘‘ (القرآن)میں نے کاغذ میز پر ہی رہنے دیا اور کمرے سے نکل آیا۔ صحن کے مغربی گوشے میں دیودار کے خوشبو دار پیڑ کے نیچے دو وجود محوِ مناجات تھے۔ دھیرے دھیرے چلتا میں صحن کے مشرقی پہلو میں بہتی آبِ جُو تک پہنچا۔ وضو کیا۔ وضو کے بعد نگۂ تشکر اٹھائی تو ستارۂ سحری آسمان کی چھت پر فانوس کی مانند جگمگا رہا تھا اور بادِ نسیم کے جھونکے بڑی سنجیدگی سے بغل گیر ہوتے اور متانت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔نمازکے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی پاس ہی موجود ہے۔ گھوم کے دیکھا تو دونوں ماں بیٹی تھیں ۔ سپیدۂ سحر نمودار ہونے کو تھا۔ مریم نے والہانہ انداز میں اپنا سرمیری گود میں ڈال دیا اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں پدرانہ شفقت کے مارے بے اختیاراس کی ریشمی زلفوں میں سرکنے لگیں ۔ ملگجے اجالے میں آمنہ کا چہرہ زردی اور نقاہت کے ہوتے ہوئے بھی دمک رہا تھا اور ایک آزردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آبُراجی تھی۔ شبنمی گھاس پر ہم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ دھڑکنیں اور خیال یکساں تھے اور ایک اکائی ہونے کے شانت تصور سے میرا قلب لبریز ہوا جا رہا تھا۔
خدشات کے اژدھے یا تو سو گئے تھے یا پھر دل و دماغ کی منڈیروں سے کھِسک گئے ہوں گے۔ الفت اور اپنائیت بھری خاموشی ہزار گفتگوؤں سے بہتر تھی جو بڑی دیر بعد ہمیں کھوجتی ہوئی وہاں آپہنچی۔ کائنات جاگنے لگی۔ گنبدِ نیلوفری پر پرندوں کے غول تیرنے لگے۔ ندیا کی روانی کی چاپ ہماری سماعتوں تک پہنچنے لگی اور دُور جنگلوں کے اسرار کی سرگوشیاں اور بستی کی جانب سے جاگی ہوئی تعبیروں کی گونج بیداری کا پیا م ثابت ہو رہی تھیں ۔ شب کی گفتگوؤں کے چراغ اب ہوائے سحر کی سرسراہٹوں میں دن کی موجِ نور سے بدل رہے تھے۔میری گود میں سرڈالے مریم اور میرے دائیں ہاتھ کی پشت کو مانوس ملائمت سے سہلاتی آمنہ اور دل کو بے پناہ جذبوں کی آماج گاہ بناتا اور دو مختلف کمیاب لمسوں سے ممنون ہوتا مَیں ۔۔۔ شبنم، ریشم اور سرگم سے بنتا وہ تکونی بندھن ۔۔۔ جیسے تمام کائنات ہمارے گھر میں سمٹ آئی ہو۔ ’’بابا؟‘‘ سکوت کے تھال پر پہلی ضرب پڑی۔ ’’جی!‘‘’’محبت کیا ہے؟؟‘‘مجھے لگا جیسے یک دم سانپوں سے بھرے کنویں میں گر گیا ہوں ۔ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔مضروب کی مانند خاموش رہا۔ یہ سوال جو بہ ظاہر اتنا بھی انوکھا نہ تھا لیکن ایک بیٹی اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کا سوال تھا۔ مجھے خطرناک لگا ۔ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں سن ہو گئیں ۔ میں نے آمنہ کو مدد طلب نظروں سے دیکھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی اور جیسے ہم سے خبر اپنی کسی گھمبیر سوچ میں مگن تھی۔ ’’میری بچی! محبت ۔۔۔ محبت وہ کیفیت ہے جس میں انسان مبتلا ہو جائے تو دانستہ نا دانستہ باہر آنے کوجی نہ چاہے۔ جس سے ہو تو اس کے بغیر رہا نہ جائے۔ یہ ایسی ہے جیسے مجھے تم دونوں سے ۔ جس طرح تم دونوں کو مجھ سے ۔۔۔ جس سے ہو وہ محبوب اور جسے ہو وہ محب۔ اور ہم بیک وقت محب بھی ہیں اور محبوب بھی‘‘’’یعنی وہ ارادت جو محب کو محبوب بنا قرار نہ لینے دے۔ دیدار کی خواہش ہو۔ ملاقات کی تمنا ہو اور رہا نہ جائے۔ یہ تو سر اسرمجاز کی بات ہوئی نا بابا‘‘اب سارے سانپ معدوم ہو گئے ۔ میں الجھن کے کنویں کی تہہ تک جا پہنچا۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جس کے بیش تر لمحاتِ زیست میرے سامنے گزرے تھے۔ یہ وہ مریم نہیں رہی تھی ۔ بیج سے پودا بنتا ہے لیکن ساری تبدیلیوں کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی چاہے نظر مسلسل کیوں نہ ٹکی رہے۔’’میں تو آج تک صرف ایک ہی صورت حال میں رہتا آیا ہوں بیٹا۔ آپ بتا دو کہ دیگر صورتیں کون سی ہیں ؟‘‘’’محب کا اپنے اختیار کو چھوڑدینے اور محبوب کے اختیار میں چلے جانے کا نام ہے محبت‘‘میں نے اسے مزید کریدنا چاہا: ’’محبت ذات سے ہو یا صفات سے؟‘‘’’دیدار ممکن ہو تو ذات سے ورنہ صفات سے ۔محبت دراصل ذات سے ہی ہوتی ہے۔ مجاز میں ذات کا ادراک ممکن ہے جبکہ لا مجاز میں ذات کا ادراک نا ممکن۔ میں نہیں کہتی ۔ سُنا ہے کہ عشق بغیر مشاہدے کے ناممکن ہے جب کہ محبت خبر سے بھی ہو جاتی ہے
‘‘یہ کس نے فرمایا؟‘‘
’’ہمارے شیخ نے‘‘
اتنا کہہ کر وہ اُٹھی اور چلی گئی۔
میرے ذہن پر تحیّر کے ہتھوڑے برسنے لگے۔
’’یہ مریم کو کیا ہو گیا آمنہ؟‘‘’’وہی جو وہ کہہ گئی ہے‘‘’
’کیا یہ بھی خانم کی صد فسونی کا نتیجہ ہے یا مریم کا اپنا فیصلہ؟‘‘
’’فہیم! قدرت بعضوں کے ذوقِ نظر کو بلند کر دے تو کئی برسوں کے مرحلے بغیر چُنی ہوئی دیوار کی طرح آپوں آپ ڈھے جاتے ہیں ۔
پھر نگۂ کرم کی روانی سے آشنائی میں کوئی شے مانع نہیں رہتی۔ وہ جو اپنے ظاہر کے گرد آگ بھڑکا کربیٹھ رہیں تو شوق کے آتش کدے باطن میں بجھ جاتے ہیں ۔ اپنے آپ سے نکل آنے میں بڑی یافت ہے فہیم !۔۔۔ عمر کی کوئی شرط نہیں ۔ بس چناؤ کا چمتکار ہے‘‘’’اس کی محبت کا ہدف کون ہے؟‘‘’’جذبۂ محبت کی راہ میں کئی شرطیں بیٹھ جاتی ہیں ۔ بہت سے امکانات کو بے پَر کے اُڑ کر عبور کرنا پڑتا ہے ۔ کئی کہکشاؤں کی گرد پھانکنی پڑتی ہے ۔ آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا ہر گز نہیں ۔ وہ قوسِ قزح کے جھُولے پر نہیں جھولی۔ شبیہہ تمثیل میں قید رہ سکتی ہے اور نہ ہی وجود۔ جستجو کی دہلیز پر کئی سجدے اپنی مراد کو جا پہنچے ہیں ‘‘’’تم تینوں نے میرے خلاف کونسی گھناؤنی سازش تیار کر رکھی ہے؟‘‘جواباً وہ ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی اورمیں دیکھتا چلا گیا۔ آنسو ڈھلکتے چلے گئے ۔ پھر اس نے کمال لطافت سے اپنے ہاتھ کو میری جانب بڑھایا تو میں نے یتیموں والی بے بسی کے ساتھ خود کو اس کے برتاؤ کے سپرد کر دیا۔ شجر چاہے اندر سے جتنا بھی کھوکھلا ہو اس کی چھاؤں دینے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ چھاؤں کی خنکی متاثر نہیں ہوتی۔
آمنہ کی قربت ویسی ہی تھی جیسی وہ برسوں سے دہکتے انگار واہموں پر شبنمی پھوار برساتی آئی تھی۔ ہم نفسی کا یہ احساس یوں تھا جس طرح شفا اور دوا کی مفاہمت سے روگ ختم ہو جاتے ہیں یا جب رات کے رخسار پر بوسہ لے کر دن بیدار ہو جاتا ہے۔’’میں نے ندیا پار کے جنگل میں ایک انوکھا منظر دیکھا تھا۔مریم کی باتیں مجھے اس منظر کی شرح معلوم ہوتی ہیں ۔ میرا خیال ہے کہ محبت صفات سے ہوتی ہوئی ذات کی طرف بڑھتی ہے۔ درست ہے نا آمنہ؟‘‘’’ہاں فہیم! ایک صورت تو یہ ہے کہ محب، محبوب کے احسانات وانعامات کا مشاہدہ کرے۔تسلیم و رضا کو پپہنچے تو یوں صفات سے محبت ہوئی اور دوسری صورت یہ کہ محب انہیں حجاب جانے اور ان کی بہ دولت محبوب کی ذات کو اپنا مقصود و مطلوب ٹھہرائے۔ مجاز میں محبت شے کے ساتھ جب کہ لامجاز میں شے کی لاشے کے ساتھ قرار پکڑتی ہے۔ پہلی نوعیت میں ابہام اور شبہات باقی رہتے ہیں البتہ ادراک نہیں ہوتا لیکن دوسری نوعیت میں اُٹھ جاتے ہیں اور اعتبار بھی مل جاتا ہے‘‘’’وہ چیچک زدہ کُبڑا در یوزہ گر اور اس کے مقابل بیٹھی خوش رُو اور خوش خُودوشیزہ ، جانے وہ کون تھے اور کن زمانوں سے وہاں موجود ہیں ۔ اُن دونوں کی باہمی گفتگو میں میرے لیے اسرار، دانش بھری وابستگی اور جانی پہچانی اپنائیت تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھے؟ تم نے کبھی وہ لَے سنی جو شب کے سناٹوں میں یادن کے سکوت میں سنائی دیا کرتی ہے؟۔۔۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو اس بانسری کا مالک ہے‘‘’’وہ نمائندۂ تشریفات ، وہ کوچہ گرد، وہ درویش اور مختلف بہروپوں والا جو ہمیں مختلف اوقات اور مقامات پر ملتا رہا۔ وہ۔۔۔۔۔ اور وہ دوشیزہ ۔۔۔۔‘‘؟’’ہاں ۔۔۔ ہاں ۔۔۔ وہ کون تھی بھلا؟‘‘’’ہماری بیٹی‘‘’’مریم؟‘‘ میں دوبارہ سانپوں بھرے کنویں میں جاگرا۔ ’’نہیں آمنہ وہ مریم کیسے ہو سکتی ہے۔ کیامیں اُس وقت کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔‘‘؟’’آپ اگر ایک ہی مرد کو مختلف بھید بھاؤ میں دیکھ سکتے ہیں تو مریم کو کیوں نہیں ‘‘’’یہ سلسلہ کب آغاز ہوا؟‘‘’’اُن برسوں میں جب ہم یہاں آکر آباد ہوئے۔ تب مریم بہت چھوٹی تھی۔ ندی پر جب میں کپڑے دھویا کرتی تو یہ میرے پہلوسے لگی رواں پانی پر سنگریز ے اچھالا کرتی اور دُور کے جنگل سے وہ نواسنائی دیا کرتی جسے آپ ’’آوازِ دوست‘‘ سے مشابہ ٹھہرایاکرتے تھے۔
سنگریز ے اچھالنے کا معمول تب تک تھما رہتا جب تک کہ وہ لَے تھم نہ جاتی۔ محبت کا بیج بھی وقت چاہتا ہے ۔ اچانک نہیں اگتا۔ اپنے متعینہ لمحے کا منتظر رہتا ہے ۔ دل کسی گمنام قربت کے انتظار میں مامون رہتا ہے حتیٰ کہ حُب کے تمام مصائب یکے بعد دیگر ے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں ۔ آرزو جو بہت خوشگوار معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے اصل میں بے ثبات ہے اور بے ثبات چیز کبھی جمیل نہیں ہوتی ۔ آپ نے مریم کی آرزو کو دیکھا جو اس کے مقابل تھی۔ جمیل نہ تھی اگرچہ آپ سے جُڑی مقصدیت کا سحر جمیل تھا ۔محبت اصل میں آرزو سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ اس نے شبیہہ کو دیکھا جو تمثیل میں پابند تھی وجود نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے فہیم کہ شبیہہ ہو یا وجود دونوں پابند رہ سکتے ہیں مگر روح نہیں۔‘‘’’اور خانم محبت کے اس قضیئے سے آگاہ ہیں ‘‘’’جی ۔۔۔ اور رہنما بھی وہی ہیں ۔ کیا آپ بھول گئے؟‘‘’’میں کیسے بھلا سکتا ہوں ‘‘ یہ کہتے ہوئے میں نے نظر کے محیط میں آتی کائنات کو دیکھا ۔ مجھے سب سراب معلوم ہُوا۔ خواب محسوس ہُوا۔ لگا ابھی آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہ ہو گا۔ ہست کی کل کہانی عدم کا سایہ ہے اور سائے کو ثبات کہاں۔’’فہیم!‘‘’’جی!‘‘’’آج بزمِ اہل فکر کی محفل بھی ہوگی‘‘’’ہونی تو چاہیے‘‘’’آج بستی کی طرف چلیں گے‘‘’’ہاں جانا تو چاہیے‘‘’’آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے فہیم؟‘‘ایک بھولی بسری دل میں کھُبی ہوئی اَنّی بے اختیار ٹیس بن گئی۔چھُوٹا ہُوا دیار نگاہوں میں گھوم گیا۔ یک لخت اضطرابیت نے گھیر لیا۔ دیرینہ صورتوں کی یاد نے مفلوج کر دیا ہوجیسے۔ پرانی تلخیوں اور صعوبتوں نے جھنجھوڑ دیا ہو جس طرح۔ یتیمی اور تہی دستی کا احساس بھوکے شیروں کی مانند مجھ پر آن جھپٹا۔ سوتیلی نفرتوں اور استحصالیت کی چیونٹیاں بدن پر رینگنے لگیں ۔ ساتھ ساتھ چند مہربان رویوں اور ہمدردیوں کی یاد نے بھی یلغار کی۔ عمرِ رفتہ کا تلاطم اندر ہی اندر اُٹھا تو وجود یوں کپکپانے لگا جیسے بھونچال سے زمین تڑپنے لگتی ہے۔
’’تم نے یاد دلایا تو یا د آگیا‘‘’’اور وہ ڈھلوانی جنگل بھی جس میں سے گزر کر آپ پہلی بار مجھ تک پہنچے تھے۔۔۔
کیا وہ بھی؟‘‘’’ہاں وہ بھی۔۔۔ لیکن آج وہ سب تمہیں کیوں یاد آنے لگا بھئی۔ خیر تو ہے؟‘‘
’’جی چاہتا ہے ایک بار دیکھ لوں ۔ بس آخری بار فہیم۔ صرف ایک دفعہ پھر جانے کو من کرتا ہے،
اُن چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھنا ہے ۔مَیں ان چوبی سیڑھیوں پر بیٹھنا چاہتی ہوں ۔ اپنی ہاتھوں لگائے ہوئے پیڑوں کوچھُونا چاہتی ہوں ۔ اس پیڑ کو جس پر آپ نے اپنی انگشتِ شہادت کے ناخن سے کھرنچ ڈالی تھی اپس کا لمس محسوس کرنا چاہتی ہُوں۔ کچھ دیر اُس گورستان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس میں میرے اجداد خاک اوڑھے سوتے ہیں ۔۔۔ اور پتھر کی ہموار سِلوں پر بیٹھ کر نیچے جنگل کی طرف دیکھوں گی۔ ہم اس جنگل میں کچھ ساعتیں گزاریں گے جس میں خود رَو بیلیں ، چشمے ، پھول ، پرندے ، پگڈنڈیاں اور آزاد طینت جانور تھے۔ بتائیے فہیم کب چلیں گے؟‘‘ "جب تم چاہو۔کہو تو ابھی چلے چلتے ہیں"میں نے جواب دیا۔’’مجھ معاف کر دینا فہیم کہ جو عہد ہم نے مشترکہ باندھا تھا میں ہی اس کی شکنی کی مرتکب ہو رہی ہوں‘‘’’بعض وعدوں اور معاہدوں کا ٹوٹنا بہت اچھا لگتا ہے آمنہ!‘‘’’شکریہ فہیم!‘‘’’اب تکلف تو نہ ہو تو‘‘سورج اس اثناء میں مشرق کی گود سے سر اٹھانے لگا ۔ مریم نے برآمدے کے مرکزی چوبی ستون سے ٹیک لگائے صدا دی۔ ’’صاحبان! ناشتہ آپ دونوں کا منتظر ہے‘‘ہم دونوں ہنسے، اُٹھے اور مریم کی قیادت میں باورچی خانے کی طرف بڑھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۱۰- باب
باہر موسم کی سنگینی عروج پر ہے۔ گھپ تاریکی میں چہارسو پھیلی برف کی سفید چادر چاندنی کا سماں پیدا کرنے لگی ہے اور بادِ سموم کے مشتعل جھکڑاڑیل بھینسوں کی مانند دیواروں اور درختوں سے رگڑ کھا کر گزرتے ہیں ۔ انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں کی شیرِ گرم حدت سے مریم کی پیشانی پر دھیمی دھیمی نمی کا غبار ہے۔ میری بچی ، میری مریم ۔۔۔۔ اپنے گاڑھے دکھ سے مضمحل سو رہی ہے جس کے مہلک احساس کی بے دار ی سے قبل مجھے اپنے اس مکتوب کو مکمل کرنا ہوگا۔توہُوا ےُوں کہ اس وعدے کی تکمیل سے پہلے جو میں نے آمنہ سے کیا تھا، بزمِ اہلِ فکر کے سبھی اراکین کے اعزاز میں ایک وداعی دعوتِ طعام کا اہتمام کیا گیا۔ خبر ملنے کی دیر تھی کہ عین وقتِ مقرر ہ پر محبوب لوہار، حکیم نشتر انصاری، نورو ملاح، ماسٹر خوشحال سنگھ، حافظ شمسی، موہن داس سُنار، مائی خیراں اور آنسہ انجیلا آپہنچیں۔ہمارا وہ بزمِ فکر کا آخری اجلاس تھا جس کے باقاعدہ آغاز سے قبل نقیبِ مجلس آمنہ نے حافظ شمسی سے تلاوتِ قرآنِ حکیم کی درخواست کی۔ حافظ صاحب کے کانپتے ، چھچھلتے اور رعشہ زدہ مگرپُر سوز لحن نے ماحول کو عقیدت میں نہلا دیا۔
بعد ازاں انہوں نے بائبل، گرنتھ اور گیتا کے چنیدہ اقتباسات بھی نذرِ سامعین کیے۔ مریم نے رجسٹرکاروائی سنبھالا۔ صدرِ محفل کے لیے نُورو ملاح کا نام تجویز ہوا۔ آمنہ نے کہا:’
’ذی وقار حاضرینِ محفل!۔۔۔۔ خوش آمدید!!!!
آج سے سولہ برس قبل ہم اپنی واماندہ سانسوں کو خرچ کرتے یہاں پہنچے تو وقوعات کی تیز بوچھاڑ میں افتاں و خیزاں زندگی کو عارضی جائے امن ملی تھی۔ ہمیں آپ کی ہم نفسی اور ہمسائیگی کا شرف ملا اور جیون کی وہ مشترکہ مقصدیت جس کا تانابانا ہم نے مِل کر بُنا اس میں شاید ہی کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو یا اس پر کوئی لمحۂ تغافل گزرا ہو۔ اگر چہ کچھ لغویات کسی آسیب کی طرح کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ ہماری حیثیت تاحال ایک راہ رُو کی سی ہے کیوں کہ فہیم اور میرے درمیان ابتدا سے ہی یہ سمجھوتہ طے پاچکا تھا کہ کبھی کہیں مستقل قیام نہ کریں گے ۔ ہم جو اتنا عرصہ آ پ کے ساتھ اور آپ کے درمیان رہے تو ایک مقصدیت کے عوض۔۔۔ تاہم جلد ہی اپنے سلوک ،کردار‘ اور بُرے یا بھلے اطوار کی یادوں کا اثاثہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے ۔ہر کہیں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ ہم ایک امید وصل کو ہمیشہ اپنے زادِ راہ میں ساتھ رکھیں گے۔ ممکن ہے ہم کبھی لوٹ سکیں ۔ بہت ممکن ہے کبھی اپنی محبتوں کا دم بھرنے کو پھر پلٹ سکیں۔ ۔۔۔ اس لیے کہ ہم ان کہکشانی راہوں کو علامات لاموہوم جانتے ہیں جو اس بستی تک پہنچتی ہیں ۔ ہم اس کے باسیوں کی آنکھوں میں بے کراں انسیت اور مروت کی عمیق سرخی کو بارِ دگر دیکھنے کی ہمک سے سرشار رہیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں اتر آنے والی اشکوں کی چکا چوند۔۔۔ ہمیں اس زحمت کے بدلے در گزر کیجئے جو آپ کو نہیں اٹھانی چاہیے لیکن ۔۔۔۔‘‘ اور آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔اس ساعتِ گریہ کو بھی آخر کار آنا ہی تھا۔اچھی خاصی شاداں و فرحاں محفل شامِ غریباں میں بدل گئی۔ آنسوؤں ، آہوں اور ہچکیوں نے سارے ماحول کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ کوئی کسی کو دو حرفِ تسلی دینے کے لائق نہ رہا۔
تا دیر یہ کیفیت طاری رہی۔ آنکھیں نہ اٹھ سکیں ۔ سرصدمے سے جھکے رہے۔ جذباتی کشمکش سے بوڑھے وجود کپکپاتے رہے۔ مریم بند رجسٹر کو گھورے جا رہی تھی۔ اس خارجی و باطنی طلاطم کو ضابطۂ تحریر میں لانا امرِ محال تھا۔ بالآخر میرِ محفل نورو ملاح کچھ سنبھلے۔ رُندھے ہوئے لہجے اور اکھڑی سانسوں میں گویا ہوئے:’’سجنو! گو بات دکھ والی ہے مگر مان لو کہ جن کواڑوں کو بند ہونا ہے، ہو کے رہیں گے۔ جیون نام ہی اپنے ادھڑے پن کو مسلسل سیئے جانے کا ہے۔ ہم کسی نہ کسی طور ایک بے ہنگم دھن کی طرح بجتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن اس سمفنی میں جاملتے ہیں جسے موت کہا جاتا ہے۔ پھر بھی ایک عارضی بنیاد پر مستقل عمارت کی حرص سے کبھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ تعلق چاہے کسی بھی فانی اور مادی شے کا ہو، دائمی نہیں رہتا۔ دنیا سب دھوکہ ہے۔ بھرے میلے اور آباد بازار دراصل خواب کی طرح ہیں ۔ آنکھ کھلے تو غائب ۔ میرے مرشد ایک حکایت سنایا کرتے تھے کہ کوئی درویش بازار میں بیٹھا تھا۔ کسی شناسا کا گزر ہوا تو پوچھا۔ ’’خیریت؟‘‘ درویش نے جواب دیا۔ ’’بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں ۔ اللہ تو مانتا ہے بندے نہیں مان رہے‘‘ اور کچھ مدت بعد وہی درویش ایک قبرستان میں بیٹھا تھا کہ اسی دیرینہ شناسا کا گزر ہوا۔ پوچھا ’’خیریت؟‘‘ درویش رونے لگا اور بولا: ’’اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ بندے تو مانتے ہیں ۔ اب اللہ نہیں مان رہا‘‘ کتنا نادان ہے انسان کہ جس شے نے باقی ہی نہیں رہنا اس پر اپنا استحقاق جمانے بیٹھ جاتا ہے ۔ مسافر، سرائے کو ہی منزل سمجھنے لگے تو کہیئے کیا سفر جاری رہ سکتا ہے؟ ۔۔۔ نہیں نا؟ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رشتے ناطوں کے کاروان گزر گئے۔ میں آج اسی برس کا ہوں۔ ایک دن میری ہی ناؤ پہ سوار یہ تینوں یہاں پہنچے اور یہاں قیام کا قصد کیا تو میں جان گیا کہ ہمارے ٹاٹ کے لباسوں میں یہ مخملی پیوند زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ یہ اپنی کہکشان سے بچھڑے وہ ستارے ہیں جن کی مسافت نا تمام ہے۔ کچھ دیر کا ساتھ ہے۔ ان کی آمد سے وادی کی بنیادوں میں دبی ہوئی گم شدہ مسکراہٹوں اور مسرتوں نے سر ابھارے اور مدتوں کی یکسانیت خوردہ زندگیوں نے تبدیلی کی کروٹ لی۔ یہ ہمارے قصبے کی شہ سرخی بن گئے۔ ہم پہلے اپنے اپنے انفرادی معمولات میں غرق تھے۔ یہی تھے جنہوں نے ہمسائیگی اور ہم نفسی کی سعادتوں سے روشناس کیا۔ ہم پر ہماری مخفی صلاحیتوں کا انکشاف کیا۔ کون جانتا تھا کہ محبوب لوہار ایک شاعر، حکیم انصاری انشاء پر داز اور انجیلا قصہ گو ہیں ۔ مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے ۔ میں فرداً فرداً سب کو دعوت کلام دوں گا۔ آج کوئی متعین موضوع نہیں ہے۔ جو جس پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، کر سکتا ہے ۔
پہلے محبوب صاحب آپ!۔۔۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟‘‘۔محبوب پہلے جھینپ گئے کہ طبعاً شرمیلے واقع ہوئے تھے پھر اپنے نیلے رنگ کے صافے سے اپنی نم آنکھوں کو خشک کیا۔ ہولے سے کھنکارے اور ساری محفل پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور چندھیائی ہوئی نظر نچھاور کر کے بولے:’’شکریہ!۔۔۔۔ میرِ مجلس۔۔۔! آپ نے عزت دی۔ مجھے شاعر کہا۔سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ۔ ساری عمر تو لوہا کُوٹتے اور آپ لوگوں کی چارپائیوں، کرسیوں ، میزوں اور پیڑھیوں کی چولیں بٹھاتے گزر گئی۔ میں ایک کھنڈر تھا۔ مجھے تو ان تینوں نے دریافت کیا۔ ایک مدت انحرافات میں گزری اوربقیہ سراسر تسلیمات میں گزر رہی ہے۔ جو ہر شناس یہ سامنے بیٹھے ہیں ۔ اب دریافت شدہ اپنے دریافت کنند گان کے سامنے کیا کہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا۔ بہت تمنا تھی بچوں کی۔خدا نے پوری کر دی۔ آمنہ اور فہیم نے مجھے حقیقی با پ کی طرح عزت دی۔۔۔۔ اور ایسی عزت کہ سگی اولاد ہوتی تو کبھی نہ دے سکتی۔ خدا نے میر ی آرزو کا سُود بھی مجھے عطا کیا۔ مریم کی صورت میں ۔ میں بہت خوش جیتا آرہا تھا۔۔۔ مگر ۔۔۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے ۔ آپ نے بجا فرمایا کہ تعلق کسی بھی شے سے ہو، دائمی نہیں رہتا۔ ماسٹر خوشحال سنگھ میرا بچپن کا بیلی، اس کے پانچ بیٹے اسے جیتے جی چھوڑ گئے۔ وہ پھر بھی زندہ ہے۔ ہم سے زیادہ ہنستا اور قہقہے اڑاتا ہے۔ ۔۔۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح ۔۔۔۔۔‘‘محبوب لوہارنے ساری محفل کی طرف سے منہ پھیر لیااور سب اس کے تھرتھراتے ، جھٹکے کھاتے اور ہلکورے لیتے وجود کو بے بسی سے دیکھنے لگے ۔ میرمجلس نے اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ جمائے اور اپنے گریبان میں جھانکنے لگے۔ ماسٹر خوشحال سنگھ دریدہ مسکراہٹ سمیت محبوب لوہار کی پیٹھ سہلانے لگے۔ محفل کو قدرے قرار آیا تو میرِ مجلس نے آنسہ انجیلا کی جانب دیکھا اور سر کی خفیف سے جنبش سے انہیں سے انہیں بہ زبانِ خاموشی دعوتِ گفتگو دی۔ انجیلا کا گورا چٹا جھریوں بھرا چہرہ کسی باطنی جذبے کی یورش سے پہلے دمکا پھر سنجیدگی کے تیوروں سے مدہم پڑ گیا ۔ انہوں نے کچھ کہنے کو لب واکیے ہی تھے کہ رک گئیں اور اس عالم میں ان کا منہ کچھ ثانیے کو کھلا رہ گیا۔ فوراً ہی انہوں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ کہنے لگیں :’’موضوع تو میرِ مجلس خود بخود طے ہو گیا یعنی ٹرمینل ڈیپروائیویشن ۔۔۔۔ میری مراد ’یقینی ہجرت‘ سے ہے۔ بہت کٹھن موڑ ہے۔ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ سچ بات ہے ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر اس امتحان سے بھی کبھی گزرے گی۔کوئی ساٹھ پینسٹھ برس قبل ہم اطالیہ سے یہاں پہنچے۔ میں ، میری ماں کیپریکااور میرے والد سیموئل جو ایک مشنری تھے۔ اُس وقت میں نوخیز تھی اور والدین کی کڑی تربیت اور تعلیمات کی بہ دولت نن بننے کی آرزو مند تھی۔ جانتے ہیں نا آپ کہ اس بستی کے شمالی سرے پر، ندی کے کنارے جو بڑی کھگر نما چٹان ہے۔ اس کے پاس ہی بہت خوبصورت لکڑی اور پتھروں سے تعمیر کردہ گر جا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس بستی میں مخلوط نسلوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی کثیرتعداد آباد تھی۔ ہندو سکھ اور مسلمانوں کے علاوہ مٹھی بھر بدھ مت والے بھی مگر نہ زبان کے جھگڑے، نہ مذہب کے نام پر فسادات اور نہ ہی نسلی امتیاز کے بکھیڑے تھے۔ ہم نے بہت تھوڑے عرصے میں یہاں کی مقامی بولی کے لب و لہجے پرعبور حاصل کر لیا۔ میری ماں حمل سے تھیں ۔ یہاں پہنچنے کے ٹھیک سات ماہ بعد وہ زچگی کے دوران ہی فوت ہو گئیں ۔ اس صدمے نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا۔ اس کیفیت سے نکلنے میں بہت دیر لگی۔ بہرحال معمولات بحال ہو ہی گئے۔ کوئی سال بھر گزرا کہ تقسیم کی خبریں آنے لگیں ۔ سینتالیس (1947) آیا اور گزر گیا۔ بستی کی بیشتر ہندو آبادی ہجرت کر گئی۔ بہت سے سکھ اور عیسائی خاندان بھی چلے گئے ۔ گرجے میں عبادت کے لیے صرف تین لوگ رہ گئے۔ ہم باپ
بیٹی کے علاوہ تیسرا ینگلو انڈین سمپسن ناصر جو ایک محبوط الحواس شخص تھا۔ وہ کچھ عرصہ تو باقاعدگی سے آتا اور تمام مذہبی امور میں حصہ لیتا رہا پھر اچانک وہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک کوئی خبر نہیں ملی ۔ میرے والد مزید پانچ سال اور جیئے ۔ بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک دن طبیب سے دوا لینے گئے اور ندی پار کے جنگل کی دوسری جانب بڑے قصبے سے واپس لوٹ رہے تھے کہ گرے اور دم توڑ دیا۔ ان کی قبر قصبے کے گرجے کے احاطے میں واقع ہے ۔جب کوئی ہم مذہب نہ رہا تو میرے سامنے دو راستے رہ گئے ۔ یا تو اپنے وطن لوٹ جاؤں یا پھر۔۔۔۔ میں نے ڈگر بدلی۔ درس و تدریس کا انتخاب کیا ۔گرجا چھوڑا اور اپنی منہ بولی بہن جو ہمارے درمیان موجود ہیں ۔ مائی خیراں کے ہاں اُٹھ آئی۔ شادی نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ویسا ملا ہی نہیں جیسا من چاہتا تھا اور اب کوئی حسرت یا خلش بھی نہیں ۔ دل کو آرزو سے بے نیاز ہوئے زمانے گزر گئے۔ البتہ ایک طلب ضرور ہے۔ وہ یہ کہ موت آئے تو میری آنکھیں مکہ اور مدینہ کی زیارت سے سیراب ہوں ۔ دیکھ رہی ہوں کہ آپ چونک اٹھے ہیں ۔ دل تھام کے میرا اعتراف سن لیجئے۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں ۔ اس انقلاب کی ساری تفصیل نہ بتا پاؤں گی۔ یہ جو مریم ہے۔۔۔۔ میں اس کی معلمہ ہوں۔ ۔ میں اس کی غیر معمولی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئی اور چاہا کہ اسے اپنی راہ یعنی جادۂ تثلیث پر چلاؤں۔ میں نے کوشش کی لیکن اس بچی کے حیران کن سوالوں نے مجھے متفکر اور ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ چیلنج دے دیا اس نے ۔تحقیق اور جستجو کی طرف موڑ دیا مجھے۔ میں نے دستیاب سارے پیمانے برتے۔ ساری دلیلیں اور دعوے بے بس ہو گئے۔ میں لاجواب ہو گئی۔ تسلیم کی خُو مجھے ورثے میں ملی ہے۔ نسلی اعلیٰ ظرفی سے محروم نہیں ہوں ۔ لہٰذا میں نے کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ میرے ہاتھ ایک نتیجہ آیا کہ عقیدۂ تثلیث ہر گز الہامی نہیں ہے۔ یہ وہ معمہ اور گورکھ دھندہ ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہ گمراہ کن انسانی دماغوں کی خیانت کا شاخسانہ ہے۔ جس رات میں فیصلہ کر کے سوئی کہ اب خدائے واحد کی بادشاہی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گی تو اسی رات ایک باوقار اور حسین و جمیل خاتون میرے خواب میں آئیں ۔ بے پناہ محبت سے ملیں ۔ مبارک باد دی اور میرا نیا نام تجویز کیا۔ صبح خدیجہ بیدار ہوئی تو انجیلا مر چکی تھی۔۔۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں ۔۔۔۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پاؤں گی‘‘
خدیجہ اپنے آخری الفاظ کے اختتام کے ساتھ ہی اٹھیں اور آہستہ قدموں چلتی ہوئی پہلے مریم کو گلے لگایا اور پھر آمنہ سے آلپٹیں ۔ مجھ سمیت باقی مرد اراکین ششدر بیٹھے اس نئی صورتحال کو مضطرب انداز میں دیکھتے رہ گئے۔ میرِ مجلس نے مسکرا کر خدیجہ کی جانب دیکھا اور ایک اطمینان بھری آہ کھینچ کر بولے:’’جنابِ اقبالؒ فرما گئے:کہہ گئی رازِ محبت پردہ داری ہائے شوقتھی فغاں وہ بھی جسے ضبطِ فغاں سمجھا تھا میں بہت مبارک ہو خدیجہ بہن!۔۔۔ اور نہایت خراجِ تحسین اس بچی مریم کے لیے ۔ میں محض ناؤ ہی چلاتا رہ گیا اور بازی لے گئی یہ چھوٹی سی لڑکی۔ سچ کہا کہنے والے نے کہعشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہّ تماماس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں اور اب بھائی موہن داس جی! آپ کچھ فرمانا چاہیں گے ؟‘‘کسی گمبھیرتا سے ہڑ بڑا کر موہن داس نکلے، سنبھلے اور سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرکر گویا ہوئے:’’اجی میرِ مجلس! فرمائیں وہ جن کے مرتبے بلند ہیں ۔ میں جاتی کا شودر، کہاں میری مجال کہ آپ جیسے مہان بُدھی والوں کے سامنے اپنے چھوٹے منہ سے بڑے بول کہوں۔ ابھی جوآپ نے مہاشے اقبال جی کے اشلوک سنائے ۔تھے تو وہ بھی جاتی کے برہمن پر مزاج کے گو تم ۔۔۔ جنھوں نے اپنے دھرم اور دیس واسیوں کو گوتم کی طرح سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا اور ہمت جگائی۔ میں جانوں کہ مرگ سے سوال کرنے کا گُر جیون کی سوچ سے ہی آیا۔ ہماری جاتی نے اونچے استھان والے برہمنوں کے ہاتھوں بہت کشٹ سہے۔ ہم پر ہر اچھی بات اور ان مول شبد کے لیے دروازے بند تھے۔ پرنتو لمبی کتھا ہے سرکار! چند بولوں میں کہاں نبٹے گی۔ ’رِگ وید‘ میں لکھاہے، جب انسان من کے لوبھ سے مُکتائی پالے تو کل پہر یہی سوچنے لگتا ہے کہ وہ کون ہے، کیوں ہے اور کہاں سے آیا؟ ایک سمے تک میں خود نہ سمجھ پایا کہ آدمی چلتا ہے یا راستہ؟ میں نے سارے دھرموں کے بارے بہت بچا رکیا ۔ کھوج کی۔ ’مرکچھ کٹک‘ کا فسش بھکشو کہتا تھا کہ سر اور منہ کا منڈوانا تب تک اکارت ہے جب تک من کو نہیں منڈوایا میں مانوں کہ شروع میں سب ایک تھا۔ یہ بھید بھاؤ کا پاکھنڈ نہیں تھا۔ بعد میں تو پیٹ پوجا اورللک لوبھ کے کارن ہُوا۔ قرآن شریف میں ہے ۔ جب موسیٰ ؑ جنمے تو ان کی دائی نے فرعون کے خوف سے انہیں جل میں بہا دیا مگر ایشور کے کام نرالے ، ان ہی کے دشمن سے رکھشا کرائی۔۔ اور سر ی کرشن جب یشودھر اکی گود سے نکل کر ندی کے حوالے ہوئے تو کنس سے مہان شکتیوں نے انہیں بچایا۔لیکن یہ بھید اُن ےُگوں میں کب ہماری جاتی کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکتے تھے۔ ک
وئی ظلم سا ظلم تھا۔ کسی کول ، بھیل یا دراوڑ جات کا شودر گائتری اچارن کرتے کسی پنڈت کے قریب سے بھلے خطا سے ہی سہی گزر جاتا تو انچھر اور بھگوان کی سمرن کے کارن وہ کیا کہتے ہیں ۔۔۔۔پاپ کا بھگتان بھرنا لازم تھا۔ بھدرپرش دیوتا سمان گورو کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیتے تھے۔ ملکوتی منتروں کو سننے کی یہ کم سے کم سزاتھی۔ پرنتو آج لائبریریاں بھری پڑی ہیں اور بھگوان کی کرپا سے جس بستی میں فہیم ، آمنہ اور مریم بٹیا جیسی سندر سروپوں کا ساتھ ہو تو جیون آپوں آپ سپھل ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو پریم ہی پریم ہیں ۔ ان کے انگ انگ میں سیندور کی رچنا ہے۔ یہ جان کر من بہت بے کل ہے کہ یہ کسی اور جگ کی یاترا پرتُلے بیٹھے ہیں ۔ اپنی جاتی کے مقدر میں تو ہمیشہ کا کشٹ لکھا ہے۔ ایک اور کشٹ سے پالا پڑ گیا تو کیا پرواہ۔ مکتی تو ملتے ملتے ہی ملے گی۔۔۔ ہمارا کام تو دعا دیئے جانا ہے۔ جہاں رہیں ، سکھی رہیں ۔
بس سرکار! اور کچھ نہیں کہنا مجھے۔ پہلے ہی بہت سمے لے لیا‘‘موہن داس کے بعد میرِ مجلس نے ساری محفل پر ایک اچٹتی ہوئی طاہرانہ نگہ دوڑائی اور حکیم نشتر انصاری پر ٹھہرا کر تبسم فرمایا۔ بولے تو لہجے میں چھیڑنے والی ظرافت عیاں تھی:’’بھائی انصاری! آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ۔۔۔؟‘‘’’انصاری اگر پتھر ہوتا تو تب بھی بول پڑتا کیونکہ جس ادا سے آپ پوچھتے ہیں ، وہ ادا ہی کچھ اور ہے‘‘ حکیم صاحب بے باک واقع ہوئے تھے۔ میرِ مجلس کو جواب دے کر انہوں نے چٹکی بھر سونف پھانکے۔
ناک کی پھننگ تک آئی ہوئی عینک کے اوپر سے ناقدانہ طور پر جائزہ لیا۔ پیٹ کے زور پر اپنی شہرۂ آفاق مختصر ترین ہنسی ہنسے۔ پھسکڑا مارے بیٹھے تھے لٰہذا اسی طرح بیٹھے بیٹھے آگے پیچھے ہلے۔ بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو زور زور سے تھپتھپایا اور مزیدبولنے پر آگئے:’’آج جو کچھ سنا اور دیکھا وہ رائیگاں جانے کے لائق نہیں۔ کیوں کہ آج وہ بھید بھاؤ آشکار ہوئے جو نہ ہوتے تو میرا زُعم ناخالص ہی رہتا جسے میں خالص سمجھتا آیا ہوں کہ اپنے قریب کے ہم نفسوں سے میری جڑت بہت گہری ہے۔۔۔ بہت کچھ میں نے بہت غور سے سنا۔ جس سے اختلاف یا اتفاق کا مجھے حق حاصل ہے۔
چند باتیں میں اپنی من مرضی کی بھی کہنا چاہتا ہوں۔۔۔ عموماً یہ تصور ہے کہ زندگی کے کھیل کے سارے اصول پہلے سے طے شدہ ہیں ۔ واقعات اور حادثات کا ہونا کوئی المیہ نہیں بل کہ مقدر کے اٹل قاعدے کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مخصوص زماں اور مکاں کے چوکھٹے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہماری تمنائیں، جذبات اور تجربات ہمارے انفرادی اور ذاتی فیصلوں کے تابع نہیں ہیں ۔ اس لیے کہ ہمارے فیصلے بھی تقدیر کے پابند ہیں ۔ یعنی موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں ۔۔۔ مگر۔۔۔ میرِ مجلس! مجھے کچھ تلخ نوائی سے معاف رکھیئے گا۔ مجھے نہ کسی کے عقائد سے کوئی نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو میرے عقائد سے ۔
میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو زندان ئتقدیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سب کچھ ہی طے شدہ ہے تو انسانی محنت و مشقت سے کوئی فائدہ؟ عذاب و ثواب کے بحث مباحثوں سے کچھ حاصل؟ رجائیت اور قنوطیت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت؟۔۔۔۔خواہ مخواہ عشق و سرمستی کے نعرے لگانے کی کوئی منطق؟۔۔۔ کوئی ہو تو ہو، میں ایسی شرط اور قید کاقائل نہیں۔۔ میں اپنے شوق سے اس دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی ہنسی خوشی یاروتے بسورتے جانے میں میری مرضی کا کوئی دخل ہوگا۔ زندگی کے سیاق و سباق اور پیش منظر وپسِ منظر میں انسانی منشاء کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ پھر میں محدود اختیار پر کیوں اکتفا کروں جس پر آپ سب شاکر و صابر ہوئے بیٹھے ہیں ۔ ۔۔ میں کیوں کسی ایسے آفاقی منصوبے کا کل پرزہ بنوں جس سے نہ میں پہلے آگاہ تھا اور نہ اب ہوں ۔ یہ عجیب منصوبہ ہے جس میں نہ مجھے میری پسند کے ماں باپ ملے، نہ بیوی ملی اور نہ ہی اولاد ۔ یہ کوئی سلیقہ ہے جینے کا کہ پہلے ہر کوئی میری اصلاح کرتا تھا اور اب میں دوسروں کی اصلاح کرتا پھروں۔ تخلیق کی اس ساری کہانی میں میرا کردار بہت ناگوار ہے۔ میرا آہنگ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جو کائناتی چار دیواری سے باہر لے جانے میں میری رہنمائی کر سکتا ہو؟ ۔۔۔ کسی کے پاس نہیں ہے ۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں فرار ہو جاتا۔ سب اپنے اپنے کھونٹوں سے بندھے جگالی کر رہے ہیں ۔ افسوس میں ایسی موت مارا جاؤں گا جو میرے مطلب کی ہر گز نہیں ہو گی۔‘‘حکیم صاحب ذرا دم لینے کو رکے۔ چند گھونٹ پانی پیا اور اپنی شیروانی کی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ محفل میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی توکانوں کے پردے پھٹ جاتے۔
جلد ہی انہیں اپنا گوہرِ مقصود مل گیا۔ گول سی ڈبیہ سے چٹکی بھر سونف پھانکنے کے بعد انہوں نے وہی پیٹ کے زور پر ہنسی ہنسنے کا معمول دہرایا اور ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑ کر بولے:’’میرِمجلس! آپ سمیت سبھی مجھ پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ میں کیا بکواس کئے جا رہا ہوں۔ مگر آپ میری مراد کو نہیں پار ہے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ ہر گز مذہب کی تخفیف یا خدا کی تکذیب کی رُو سے نہیں کہا۔ میرا اشارہ اس جوہرِ نایاب کی طرف ہے جو علوم اور تہذیب کے فروغ کے لیے از بس لازم ہے۔ مجھے مذہب سے کوئی گلہ نہیں چاہے یہ مخاصمت ہو سکتی ہے چاہے وہ انسان کی جرأت تدبیر سے خوش ہو یا ضبط کر دے۔ دراصل اپنے مؤقف کا اظہار سیدھے سادے طریقے سے کردیا جائے تو توجہ کا رض زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ سواپنا یہ خانہ ساز حربہ ہے کہ پہلے طیش دلاؤ پھر عیش کراؤ" اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب نے زور کا قہقہہ لگایا اور ساری محفل نے سکون کا سانس لیا۔ شام کے سائے ان کی عینک کے شیشوں میں جھانکنے لگے تھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دیدبان شمارہ ۔۶
پسِ غبار سفر
خالد قیوم تنولی
(چوتھی قسط)
باب - 8
’’بزمِ اہلِ فکر‘‘ کی پہلی باقاعدہ تقریب کا انعقاد ہوا لیکن میں دانستہ شامل نہ ہُوا۔ آمنہ بیمار تھی اور اس کی بیماری نے مجھے ان گنت وسوسوں سے دو چار کر دیا تھا ۔ اُسے دھیما دھیما بخار رہنے لگا تھا۔ حکیم نشتر انصاری کی مُجرّب دوائیں بھی رائیگاں جا رہی تھیں ۔ ایک جانکاہ تشویش مجھے زمین میں زندہ دھنسائے جاتی تھی۔ ندیا کے پار گھمبیر اسرار والے جنگل کی دوسری جانب ایک بڑے قصبے میں کئی نامی گرامی شفا خانے تھے اور ماہر معالج بھی مگر آمنہ نہ مانتی تھی۔ میرے بار بار کے اصرار کے باوجود وہ خود اختیار لا پرواہی سے مسکرانے لگتی اور یوں ظاہر کرتی گویا دنیا کا کوئی بھی مرض اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ مگر بہ خدا ایسا نہیں تھا۔ میں چوری چھُپے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور تمام علامتیں اور تأثرات بھانپ رہا تھا جنہیں وہ مجھ سے چھپانے کی حتی الوسعیٰ کوشش کرتی۔ میں بہ خوبی جان رہا تھا کہ ہمارے لیے اس کی توجہات میں دن بہ دن کمی واقع ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا گریز اس نے خود کو لاحق کر لیا تھا ۔۔۔ اور یہ بہت اندو ہناک تغیر تھا جو ہمیں دھیرے دھیرے گھیرتا چلا جا رہا تھا ۔ وہ ہمیں پیش آمدہ حقائق اور حالات سے نپٹنے کے لیے تیارکر رہی تھی ۔ ایک مضروب بے کسی ، زخم زخم سی خاموشی، بے نیازی اورفراریت ہمارے درمیان جگہ بنانے کوپَر تولنے لگیں ۔ ردِ عمل میں وہ ساری پس انداز قوتیں اچانک جاگ اٹھیں جو کڑے وقت کے انتظار میں سوئی ہوئی تھیں۔ دو وجود نظر انداز ہو رہے تھے۔
اندیشے روح کے روزنوں سے اندروجود میں جھانکنے لگے تھے۔ ایک مثالی محبت پر وہ غم طاری ہو رہا تھا جس کی شرح نا ممکن ہے۔ وہ تمام علامتیں جو میں نے بھانپ رکھی تھیں انہیں میں نے از سرِ نوَ ازبر کیا اور آمنہ کو بتائے بغیر خود ہی معالجین سے مشاورت کی غرض سے صبح سویرے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔نورو ملاح کی ناؤ دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی ۔ وہ ایک مائل بہ حدت، غنائیہ اور اداس دن تھا۔ ناگاہ میری نظر رواں پانی پر پڑی تو دائمی خوف نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ میں نے گھبراکر نہایت روشن، اجلے اور نیلے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نورو ملاح کے بوڑھے مشقتی بازو ایک مخصوص ردِھم سے چَپّو چلا رہے تھے اور شڑاپ شڑاپ کی عمومی آواز کے سوا کوئی آواز نہ تھی ۔ ناؤ دوسرے کنارے سے جا لگی تو نُورو نے کھنکار کر بلغم کا غلفہ پُر شور انداز سے تھوکا اور دونوں بازوؤں کو ہوائی چکی کے پنکھے کی مانند گھمانے لگا۔ میں نے کُرتے کی بغلی جیب سے کچھ روپے نکالے اور اس کی جانب بڑھائے ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا پھر ایک چھچلتی ہوئی سیراب سے نظر میری مٹھی کے روپوں پرڈال کر رُخ پھیر لیا: ’’کیا تُو نہیں جانتا؟‘‘’’کیا۔۔۔ میں کیا۔۔۔ میں سمجھا نہیں بابا‘‘’’یہی کہ میں کرایہ نہیں لیا کرتا‘‘’’کیوں ؟‘‘’’کیا تُو نہیں جانتا؟‘‘’’نہیں ‘‘’’پچہتر سال ہونے کو آئے ۔ دس سال کا تھا جب پتوا رپہلی بار تھامے تھے۔ آج تک کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا۔۔۔ مرشد کا بس یہی حکم تھا۔ آج تک حکم عدولی نہیں کی میں نے‘‘’’اچھا ۔۔۔مجھے واقعی معلوم نہ تھا‘‘ میں نے تعجب سے خالی لہجے میں کہا کیونکہ ایک مدت سے مَیں حیرتوں کا عادی ہو گیا تھا۔ ’’کب تک واپسی ہو گی؟‘‘’’شام سے پہلے‘‘’’میں انتظار کروں گا‘‘’’شکریہ‘‘’’خدا کی امان‘‘اس کنارے پر سر کنڈوں کے جھنڈ تھے جن میں جا بہ جا جنگلی سؤ روں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ میری لاٹھی کی ٹھک ٹھک سے ایک ریوڑ بدک کر بھاگا۔ میں نے چند پتھر اُن کی طرف پھینکے اور اونچا اونچا انہیں بُرا بھلا کہا۔ سرکنڈوں کے جھنڈ سے باہر نکلتے ہی رستہ جنگل میں داخل ہو رہا تھا اور جنگل مختلف آوازوں سے بھرا پڑا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور درختوں میں سر ٹکراتی ہَوا کی سرسراہٹ تھی ۔ خود رو انگوروں کی بیلیں تھیں ۔ سورج کی روشنی کم کم پہنچ رہی تھی ۔ بہتے جھرنوں کی مانوس چاپ تھی جیسے سانپ رینگ رہے ہوں ۔ میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہُوا ہر شے کو اپنی یاداشت کی زنبیل میں سنبھالتا چلتا رہا۔ کہیں نمی کی بہ دولت پتھروں پر سبز کائی نے اپنی حاکمیت جما رکھی تھی اور کہیں وہ پودے بھی تھے جن کے متعلق برسوں قبل نصاب میں پڑھا تھا۔ مجھے ان پودوں کے روایتی نام معلوم نہ تھے۔ سانپ کی جلد کے چھلکوں کی طرح کے ما رکنشیا ،چاکلیٹی رنگ کے فلجے نیلا اور کھٹ مٹھے پتوں والے ایڈی انٹم اور شیر خوار بچے کے سر کے ملائم پشم جیسے گریمنی کے لچھے تھے۔
ایک مُنے سے جھرنے کے نیچے رُک کرمَیں جب چُلو بھر بھر کر تازہ، یخ اور شیریں پانی پینے لگا تو اچانک وہی برسوں کی جانی پہچانی ، پُر سوز اور مدھر، بانسری پر چھڑے کسی گیت کی کبھی مدھم اور کبھی بلند ہوتی ہوئی دھن سنائی دینے لگی ۔ کس سمت سے آرہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ اندازہ لگانا محال تھا لیکن اتنا ضرورہُوا کہ مجھ میں خاطر خواہ تونائی پیدا ہونے لگی ۔ گیت کا ایک بند پورا ہوا۔ وقفہ آیا۔ پھر ایک نسوانی ہنسی کی گونج سارے میں پھیل گئی ۔ جیسے لہروں کا گرداب ساری سطح آب کو اپنی اثریت میں لے لیتا ہے۔ اس ہنسی کے تعاقب میں کوئی قہقہہ تھا۔ کچھ دیر ماحول میں ہلچل سی رہی۔ اگلے ہی لمحے سناٹا تھا۔ پھر اس سناٹے نے ایک سوال کو میری سماعتوں کی جانب اُچھال دیا۔ ’’تم کہاں چلے گئے تھے؟‘‘جواب میں خاموشی تھی۔’’اب تو کہیں نہیں جاؤ گے نا؟‘‘وہی خاموشی۔’’بولو گے بھی یا مسکراتے ہی رہو گے؟‘‘ہنوز خاموشی۔’’مجھے یوں مت دیکھو ۔ لاج آتی ہے‘‘اب ایک نمایاں اور رفیع تر قہقہہ گونجا جس کے پسِ منظر میں مترنم ہنسی کی بازگشت بہہ رہی تھی ۔ میری آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو بے ارادہ ہنستے ہنستے اُمڈتے مجھے محسوس ہوئے ۔ ہر وہ بات جس کا ناطہ گداز اور حساسیت سے ہو، میرے آنسوؤں کولاچار اور بے اختیار کر دیتا تھا۔ سو اُس وقت وہی ہُوا جس کی مجھے امید تھی۔میرے قدم اٹھنے لگے۔’’ادھرمیری طرف دیکھو۔۔۔۔‘‘ یہ مردانہ التماس تھی۔’’کیوں ؟۔۔۔۔کیوں دیکھوں ؟‘‘’’میرے چند سوال تمہاری آنکھوں میں گِر گئے ہیں ‘‘’’سوال نہیں یہ میرے اپنے واہمے ہیں ‘‘میں ان باتوں کے حصار کے قریب ہو رہا تھا۔ تنگ، پتھریلی اور ناہموار رہ گزر پر یوں چلنے لگا جیسے چھپکلی دیوار پر رینگ رہی ہو۔ ایک مختصر سا ہری بھری گھاس کا تختہ میرے سامنے تھا جس پر دو انسانی وجود آمنے سامنے بیٹھے دکھائی دیے۔ مرد جس کے گہرے سانولے چہرے پر چیچک کے بے شمار بد نما داغ تھے۔ کُبڑا اور بد وضع، گلے میں بہت سے مالائیں، کانوں میں بالے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، پیروں میں کڑے، سیاہ لباس اور وہ بھی پیوند زدہ۔ قریب ہی ایک تھیلا ، کشکول اور لاٹھی دھری تھی۔ پہلی نظر میں وہ بد صورت غمگین اور مضحکہ خیز لگا لیکن پھر پُر کشش ، اپنائیت بھرا،پُر کیف ، رنگ رنگیلا اور متوکل محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی بانسری کو اپنے سیاہ سکڑے ہوئے ہونٹوں سے چپکائے بیٹھا تھا اور چھوٹی چھوٹی چند ھیائی ہوئی آنکھیں بند تھیں ۔ اور عورت جس کی ہنسی کی آواز میں ملفوف کرب کی تاثیر کو پا کر میرے آنسو متوحش گھوڑوں کی طرح آنکھوں سے کود پڑے تھے درحقیقت نہایت خوش رُو اور نوخیز دوشیزہ تھی ۔ اُس سمے اس کی ہنسی کسی گہرے خیال کے نیچے دب چکی ہو گی کہ وہ اپنے زانوؤں پر بائیں ہاتھ کی کھلی ہتھیلی پر داہنے بازو کی کہنی جمائے اوردائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنا آدھا چہرہ چھپائے چُپ سے ہمکنا رتھی۔ پلکوں کی جھالریں آنکھوں پر پڑی تھیں اور اس کی سیاہ لامبی زلفیں پشت سے زمین تک یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے آبشار گر رہی ہو اور پانی دُور تک بہہ رہا ہو۔ اس کا پیر ہن اس کی بے پناہ امارت کا غماز تھا۔ رنگت ایسی کہ گویا ہمیشہ دھوپ سے کنارا رہا ہو۔ وہ معمورِ شکوہ جسے صدیوں آنکھ جھپکے بنا با آسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک بہت واشگاف تضاد کی زندہ تصویر میرے سامنے تھی۔ ایسا نمایاں فرق میری آنکھوں میں رڑکنے لگا جو خواب اور سراب کے درمیان معلق رہتا ہے۔’’تم نے پوچھا کہ میں کہاں چلا گیا تھا ۔
تمہاری آنکھ کے سوالیہ زاویے میری زنبیل پر منعکس ہوتے ہیں اور میرے کشکول میں تمہارے تحیّر کے سکے کھنکھناتے ہیں ۔ تمہارا کہنا ہے کہ تمہیں رونا نہیں آتا۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ کوئی عورت بغیر اشکوں کے جی سکتی ہے ۔ تم نہ بتاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ مدتوں کی بے خودی نے مجھے اس خوبی کا حامل بنا دیا جو کسی بھی سینے کی اتھاہ زنبیل میں ہر غم کی نمی کو پرکھ لیتا ہے ۔ تو نہیں جانتی کہ میں کیوں دریوزہ گر بنا؟۔۔۔ کن جذبوں کا مجھے قحط لاحق ہے ۔ کیا تُو نہیں جانتی؟ تو وہ غنی ہے جو اگر دستِ مروّت بھی بڑھائے تو رلکِ زاروں میں نخلستان اُمڈ آئیں ۔
میری زنبیل میں کیا ہے ۔ کیا تو نہیں جانتی؟ ۔۔۔ جس میں نہ جانے کن زمانوں کی آرزوئیں پڑی ہیں ۔ کتنی حسرتوں کے جنازے بھرے ہیں ۔ کس قدر طلسم آثار آہوں کے پُرزے مقید ہیں ۔ میں کہاں جا سکتا ہوں ۔ محبت کی سطروں میں چھپا مفہوم بھی کہیں جا سکتا ہے ۔ اشکوں کی قیادت کرنے والا جذبہ بھی کبھی کھو سکتا ہے ۔ میں وہ گڈریا جو اپنی سوچوں کو طلوعِ سحر سے غروبِ شام تک دل کی بے کنار چراگاہوں میں چراتا پھرتا ہوں ۔ ۔۔۔ سوچو اگرگڈریا کہیں چلا جائے تو سوچوں کی رکھوالی کون کرے گا؟۔۔ میں سو بھی جاؤں تو یہ سوچیں میرے گرد بیٹھی میرے سانس سونگھتی رہتی ہیں ۔
ہائے ۔۔۔۔ اے ستم پسند محبت!
تیرا شکریہ۔۔۔ جس نے عین جوانی میں مجھے لاٹھی ٹیکنے کا فن سکھا دیا۔۔۔‘‘میرایوں ہونقوں کی طرح ان دونوں کو تکنا مناسب نہ تھا مگر ایک مجبور دلچسی نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس بے پناہ وابستگی اور جان نثاری کی زندہ تصویر سے اگر چہ میں باہر تھا تاہم اپنا وجود اضافی محسوس ہو رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی وقت جاتا ہے جب ان دونوں کی آنکھیں کھلیں گی اور میرا ہونا ایک ناگوارسوال میں ڈھل جائے گا اور وہ دو نایاب ترین پیکر خوشنما پرندوں کی طرح اُڑ جائیں گے اور پھر میں اپنی زندگی میں ویسا منظر کبھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ مرد خاموش ہُوا تو نو خیز دوشیزہ بولی:’’میں اپنی مٹھی کی ریکھاؤں میں تمہیں کبھی جو موہوم سا ہوتا دیکھوں پھر پوچھنا تو پڑتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ گزرے ہوئے لمحات کی یادیں بُجھے ہوئے دئیے اٹھائے ماتم کر تی نظر کے قلعے کے سامنے آبیٹھیں تو دل بے پناہ وسوسوں کی آماجگاہ ہو ہی جاتا ہے ۔ ۔۔۔ پھر میں کیوں نہ پوچھوں کہ تم کہاں چلے جاتے ہو۔ میری بیاضِ روزو شب کے بکھرے اوراق پر تمہارے قدموں کے دستخط ثبت ہیں ۔۔۔ اگر کوئی ورق ذرا سی دیر کے لیے خیال سے اوجھل ہوجائے تو کیا تشویش نہیں ہوا کرتی۔ میں اپنے واہموں سے خوف زدہ ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں کیوں پوچھتی ہوں۔ تم نے میری آنکھوں کو جن خوابوں کا عادی بنا دیا وہ مجھے رونے نہیں دیتے ۔۔۔
میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ آنسوؤں اور محرومی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔۔۔ اور یہ تعلق مجھے دو چار نہیں ہوا۔۔ مجھے اندیشوں کے اہرام میں مقیدہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگے تو روح وجود سے باہر آکر چھاتی پیٹنے لگتی ہے۔ میرے یقین کی دیوار کو آزمائش کے ناخنوں سے مت کریدو۔ ذرا بتاؤ تو شہد کی مکھیوں کو میری روح کی خبر کس نے دی ؟ میرے وجود میں خوشبو نے کیوں ڈیرے ڈال دئیے ؟ ۔ تتلیاں میری ذات کے گرد کیوں منڈلانے لگیں ۔ روشنی کے جگنو کیوں مجھے تاکنے آتے ہیں ۔ مجھے اب کیوں اس بحران کے سپرد کرنے چلے ہو جس میں سناٹے ہی سناٹے ہوتے ہیں ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس صراط مستقیم سے کنارا کرلوں جو سرا سر ’’تُو‘‘ سے ’’تُو‘‘تک لامحدود ہے۔ کیا تم سہہ سکو گے کہ میں کسی ایسی سمت کا رُخ کروں جو ہمارے مشترکہ تجربات میں نہ آئی ہو۔۔۔ مجھے میری ’’مَیں‘‘ کا سایہ بھی کب کا چھوڑ چکا۔ اب میرا اپنا کوئی انداز نہیں رہا۔ کوئی روپ نہیں رہا۔ مجھے اپنی عادت نہیں رہی۔ خود پہ اختیار نہیں رہا۔نیند میں چلتے ہوئے فرد کی راہ کا انتخاب کون کرتاہے؟۔۔۔۔ بتاؤ؟۔۔۔ مجھ سے پہلے اپنی آنکھیں کھولو۔۔۔ دیکھو! میری ذات کا آئینہ میری ہست سے انکاری ہے۔ اس میں اب میرا عکس ہی نہیں بنتا‘‘ جانے کب تک میں ان دونوں کے اسلوبِ گفتگو میں کھویا رہا جو اپنے آغاز سے منطقی و معنوی تسلسل اور ایک واضح ربط سے معمور تھی۔ ان کی تمثالیں اور کنائے شعری لطافتوں سے ہم آہنگ تھیں اور اندازِ اظہار کسی ایک کیفیتِ خیال سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے باہمی ربط میں مجھے تحیّر، تعقل، حیرت، تصادم ، تنبیہ اور تہدید کے بے شمار گوشے پنہاں دکھائی دیئے جو نہایت زیریں دلچسپی اور وفورکے بنا اُبھارے نہیں جاسکتے اور ان سے اُبھرنے والی صداقتیں ہمہ وقت زندگی کرنے کے کام آتی ہیں ،بڑی علامتوں کے ساتھ بیان ہو رہی تھیں ۔ میں نے قدم آگے کی سمت بڑھا دئیے اور اُن دونوں نے بہ یک وقت مجھے دیکھا اور مسکرائے مگر کوئی بات نہ کی ۔ وہ فقط ایک مانوس محویت کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں اپنی پیٹھ پر ان کی گداز، کریم اور مہربان نظروں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دوسری طرف کی ڈھلوان اترنے لگا اور دل پر اترتی اس منظر کی لطیف فضیلت سے مسرور اور پھر کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکنے کے تصور سے مغموم بھی ہوتا رہا۔ ڈھلوان کے حتمی موڑ پرقصبے کا قبرستان دُور تک پھیلا تھا۔ پختہ و نیم پختہ قبروں کا بے تحاشا ہجوم جس کے حُسن میں مختلف قامتوں اور رنگوں کے کتبے اضافہ کر رہے تھے۔میں نے فاتحہ پڑھ کر اپنے گمنام ہم نفسوں کی روحوں کو نذرِ ثوا ب کی اور مزید آگے بڑھنے سے قبل راہ گزر کنارے بنے ایک حوض سے پانی پیا۔گورستان کے عین درمیان پہنچ کر میں نے چاہا کہ بابُ العلم حضرت علیؓ کے وہ مصرعے دہراؤں جب انہوں نے جنگِ صفین سے واپسی پر دارلخلافے کی طرف ایک قبرستان سے گزرتے وقت فرمائے تھے:’’کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟اے وحشت زدہ گھروندوں اور اُجڑے مکانوں کے مکینو! میرا سلام قبول ہواے بے کسی کے مارو!اے خاک نشینو!تم جو تیز قدم ہم سے آگے نکل گئےاور ہم بھی بس آیا ہی چاہتے ہیں تمہارے قدموں کے نشان نشانِ راہ ہیں سنو! جو گھر بنائے تھے تم نےان میں کوئی اور بس رہا ہےجو بیویاں چھوڑی تھیں ان سے غیروں نے نکاح کر لیےاور وہ مال ہلکان ہوئے تم جس کے سببدوسروں نے کھالیا ہےیہ تو تھی ہمارے ہاں کی خبر کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟‘‘میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی پُرنم آنکھیں پونچھیں اور موت کو یاد کرتا ہُوا گورستان سے باہر آگیا۔ سامنے پکی سڑک کے پار جدید شفاخانوں کی عمارتیں کھڑی تھیں ۔
----------
باب -۹
ہماری لاکھ منتوں سماجتوں کے باوجودآمنہ نہ مانی معالجین اور طبیبوں کی وہ ساری دوائیں بھی اکارت گئیں جو بڑے دعووں کے ساتھ مجھے سونپی گئی تھیں کہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے مجرّب ہیں ۔ ہمارے بے شمار دفعہ کے اصرار کے باوجود آمنہ نے بتا کر ہی نہ دیا کہ اسے کون سا روگ لاحق تھا۔ جانے کس نا قابلِ گفت کیفیت سے نڈھال رہنے لگی۔ اس کا کروفر خدادادتھا مگر طبیعت کو جکڑتی ہوئی کسل مندی سے منہدم ہُواجاتا تھا۔ رُخساروں کی تابناکی مدھم پڑتی جاتی تھی۔ اُس کا روشن جسم گیلی لکڑی ہُوا جاتا تھا۔ لب پھیکے اور ان پر مستقل فروکش رہنے والی خفیف سی مسکان بے نام سی غفلت سے مغلوب رہنے لگی ۔اس کا بہت غنی دل بے اعتنائی کی کسک کی طرف مائل تھا۔ جن آنکھوں میں اطمینان کی چکا چوند کے میلے لگے رہتے اب یوں اُجڑتی جا رہی تھیں جیسے تند آندھی میں خیمے اُکھڑ کر اُڑ جاتے ہیں ۔۔۔ مگر وہ اعتراف سے گریزاں تھی اور ادھر ہم باپ بیٹی کے دلوں پر شبہات اور واہموں کے اژدھے کنڈلی مارے بیٹھے تھے ۔ ذرا سی خوش گمانی سر اٹھاتی تو اژدھے پھنکارنے لگتے۔ ہم تینوں بے تقصیر مجرموں کی طرح نظریں ملانے سے تغافل برتنے لگے تھے۔ بارہا میں نے دیکھا کہ مریم کسی خوفناک سناٹے سے الجھی ہُوئی خاموش آنسوؤں سے روئے جاتی ہے ۔میں نے پکارا تو بولی نہیں ۔ بس سرکی موہوم سی جنبش سے جواب دیا اور میں پلکوں پر آنسو روکے ادھر اُدھر گھومتا پھرا۔ معمولاتِ زیست جوں کے توں رواں تھے۔ کوئی خلل پیدا نہ ہو رہا تھا لیکن وقت حشرات الارض کی طرح رینگ رہا تھا ۔ مجموعی حیات بیمار کی رات ہو کے رہ گئی ۔ مسکراہٹ ہو یا نظر اپنے اپنے منبع سے بے خبر ہو گیءں ۔ جینے کی وہ ترتیب اور تہذیب جو آپ کے فیض کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوئی، زینہ زینہ بڑھتی خوش اسلوب اور خوش وضع ہوئی ، اس میں کوئی ایسا سقم پیدا ہوا جو ہماری گرفت میں نہ آرہا تھا۔ عجیب تغیر تھا۔ایسی ہی نا مطمئن، سوگوار اور بے قرار صبح صادق کو میں سو کر اٹھا تو آمنہ اپنے بستر میں نہ تھی ۔ صاف سلجھے اور بے شکن بستر کے ساتھ طرفہ میز پر ایک سبز کاغذ دھرا تھا۔ میں متجسس ہوا اور مضمحل وجود کو گھسیٹتا ہوا میز تک پہنچا۔ لیمپ کی روشنی میں میں نے وہ تحریر دیکھی جس سے میں اتنا ہی مانوس تھا جتنا کہ اپنے سانسوں سے ۔ آیتِ کریمہ درج تھی:’’ہم لوگوں کے درمیان ایام کو پھراتے ہی۔‘‘ (القرآن)میں نے کاغذ میز پر ہی رہنے دیا اور کمرے سے نکل آیا۔ صحن کے مغربی گوشے میں دیودار کے خوشبو دار پیڑ کے نیچے دو وجود محوِ مناجات تھے۔ دھیرے دھیرے چلتا میں صحن کے مشرقی پہلو میں بہتی آبِ جُو تک پہنچا۔ وضو کیا۔ وضو کے بعد نگۂ تشکر اٹھائی تو ستارۂ سحری آسمان کی چھت پر فانوس کی مانند جگمگا رہا تھا اور بادِ نسیم کے جھونکے بڑی سنجیدگی سے بغل گیر ہوتے اور متانت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔نمازکے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی پاس ہی موجود ہے۔ گھوم کے دیکھا تو دونوں ماں بیٹی تھیں ۔ سپیدۂ سحر نمودار ہونے کو تھا۔ مریم نے والہانہ انداز میں اپنا سرمیری گود میں ڈال دیا اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں پدرانہ شفقت کے مارے بے اختیاراس کی ریشمی زلفوں میں سرکنے لگیں ۔ ملگجے اجالے میں آمنہ کا چہرہ زردی اور نقاہت کے ہوتے ہوئے بھی دمک رہا تھا اور ایک آزردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آبُراجی تھی۔ شبنمی گھاس پر ہم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ دھڑکنیں اور خیال یکساں تھے اور ایک اکائی ہونے کے شانت تصور سے میرا قلب لبریز ہوا جا رہا تھا۔
خدشات کے اژدھے یا تو سو گئے تھے یا پھر دل و دماغ کی منڈیروں سے کھِسک گئے ہوں گے۔ الفت اور اپنائیت بھری خاموشی ہزار گفتگوؤں سے بہتر تھی جو بڑی دیر بعد ہمیں کھوجتی ہوئی وہاں آپہنچی۔ کائنات جاگنے لگی۔ گنبدِ نیلوفری پر پرندوں کے غول تیرنے لگے۔ ندیا کی روانی کی چاپ ہماری سماعتوں تک پہنچنے لگی اور دُور جنگلوں کے اسرار کی سرگوشیاں اور بستی کی جانب سے جاگی ہوئی تعبیروں کی گونج بیداری کا پیا م ثابت ہو رہی تھیں ۔ شب کی گفتگوؤں کے چراغ اب ہوائے سحر کی سرسراہٹوں میں دن کی موجِ نور سے بدل رہے تھے۔میری گود میں سرڈالے مریم اور میرے دائیں ہاتھ کی پشت کو مانوس ملائمت سے سہلاتی آمنہ اور دل کو بے پناہ جذبوں کی آماج گاہ بناتا اور دو مختلف کمیاب لمسوں سے ممنون ہوتا مَیں ۔۔۔ شبنم، ریشم اور سرگم سے بنتا وہ تکونی بندھن ۔۔۔ جیسے تمام کائنات ہمارے گھر میں سمٹ آئی ہو۔ ’’بابا؟‘‘ سکوت کے تھال پر پہلی ضرب پڑی۔ ’’جی!‘‘’’محبت کیا ہے؟؟‘‘مجھے لگا جیسے یک دم سانپوں سے بھرے کنویں میں گر گیا ہوں ۔ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔مضروب کی مانند خاموش رہا۔ یہ سوال جو بہ ظاہر اتنا بھی انوکھا نہ تھا لیکن ایک بیٹی اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کا سوال تھا۔ مجھے خطرناک لگا ۔ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں سن ہو گئیں ۔ میں نے آمنہ کو مدد طلب نظروں سے دیکھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی اور جیسے ہم سے خبر اپنی کسی گھمبیر سوچ میں مگن تھی۔ ’’میری بچی! محبت ۔۔۔ محبت وہ کیفیت ہے جس میں انسان مبتلا ہو جائے تو دانستہ نا دانستہ باہر آنے کوجی نہ چاہے۔ جس سے ہو تو اس کے بغیر رہا نہ جائے۔ یہ ایسی ہے جیسے مجھے تم دونوں سے ۔ جس طرح تم دونوں کو مجھ سے ۔۔۔ جس سے ہو وہ محبوب اور جسے ہو وہ محب۔ اور ہم بیک وقت محب بھی ہیں اور محبوب بھی‘‘’’یعنی وہ ارادت جو محب کو محبوب بنا قرار نہ لینے دے۔ دیدار کی خواہش ہو۔ ملاقات کی تمنا ہو اور رہا نہ جائے۔ یہ تو سر اسرمجاز کی بات ہوئی نا بابا‘‘اب سارے سانپ معدوم ہو گئے ۔ میں الجھن کے کنویں کی تہہ تک جا پہنچا۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جس کے بیش تر لمحاتِ زیست میرے سامنے گزرے تھے۔ یہ وہ مریم نہیں رہی تھی ۔ بیج سے پودا بنتا ہے لیکن ساری تبدیلیوں کی ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی چاہے نظر مسلسل کیوں نہ ٹکی رہے۔’’میں تو آج تک صرف ایک ہی صورت حال میں رہتا آیا ہوں بیٹا۔ آپ بتا دو کہ دیگر صورتیں کون سی ہیں ؟‘‘’’محب کا اپنے اختیار کو چھوڑدینے اور محبوب کے اختیار میں چلے جانے کا نام ہے محبت‘‘میں نے اسے مزید کریدنا چاہا: ’’محبت ذات سے ہو یا صفات سے؟‘‘’’دیدار ممکن ہو تو ذات سے ورنہ صفات سے ۔محبت دراصل ذات سے ہی ہوتی ہے۔ مجاز میں ذات کا ادراک ممکن ہے جبکہ لا مجاز میں ذات کا ادراک نا ممکن۔ میں نہیں کہتی ۔ سُنا ہے کہ عشق بغیر مشاہدے کے ناممکن ہے جب کہ محبت خبر سے بھی ہو جاتی ہے
‘‘یہ کس نے فرمایا؟‘‘
’’ہمارے شیخ نے‘‘
اتنا کہہ کر وہ اُٹھی اور چلی گئی۔
میرے ذہن پر تحیّر کے ہتھوڑے برسنے لگے۔
’’یہ مریم کو کیا ہو گیا آمنہ؟‘‘’’وہی جو وہ کہہ گئی ہے‘‘’
’کیا یہ بھی خانم کی صد فسونی کا نتیجہ ہے یا مریم کا اپنا فیصلہ؟‘‘
’’فہیم! قدرت بعضوں کے ذوقِ نظر کو بلند کر دے تو کئی برسوں کے مرحلے بغیر چُنی ہوئی دیوار کی طرح آپوں آپ ڈھے جاتے ہیں ۔
پھر نگۂ کرم کی روانی سے آشنائی میں کوئی شے مانع نہیں رہتی۔ وہ جو اپنے ظاہر کے گرد آگ بھڑکا کربیٹھ رہیں تو شوق کے آتش کدے باطن میں بجھ جاتے ہیں ۔ اپنے آپ سے نکل آنے میں بڑی یافت ہے فہیم !۔۔۔ عمر کی کوئی شرط نہیں ۔ بس چناؤ کا چمتکار ہے‘‘’’اس کی محبت کا ہدف کون ہے؟‘‘’’جذبۂ محبت کی راہ میں کئی شرطیں بیٹھ جاتی ہیں ۔ بہت سے امکانات کو بے پَر کے اُڑ کر عبور کرنا پڑتا ہے ۔ کئی کہکشاؤں کی گرد پھانکنی پڑتی ہے ۔ آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا ہر گز نہیں ۔ وہ قوسِ قزح کے جھُولے پر نہیں جھولی۔ شبیہہ تمثیل میں قید رہ سکتی ہے اور نہ ہی وجود۔ جستجو کی دہلیز پر کئی سجدے اپنی مراد کو جا پہنچے ہیں ‘‘’’تم تینوں نے میرے خلاف کونسی گھناؤنی سازش تیار کر رکھی ہے؟‘‘جواباً وہ ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی اورمیں دیکھتا چلا گیا۔ آنسو ڈھلکتے چلے گئے ۔ پھر اس نے کمال لطافت سے اپنے ہاتھ کو میری جانب بڑھایا تو میں نے یتیموں والی بے بسی کے ساتھ خود کو اس کے برتاؤ کے سپرد کر دیا۔ شجر چاہے اندر سے جتنا بھی کھوکھلا ہو اس کی چھاؤں دینے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ چھاؤں کی خنکی متاثر نہیں ہوتی۔
آمنہ کی قربت ویسی ہی تھی جیسی وہ برسوں سے دہکتے انگار واہموں پر شبنمی پھوار برساتی آئی تھی۔ ہم نفسی کا یہ احساس یوں تھا جس طرح شفا اور دوا کی مفاہمت سے روگ ختم ہو جاتے ہیں یا جب رات کے رخسار پر بوسہ لے کر دن بیدار ہو جاتا ہے۔’’میں نے ندیا پار کے جنگل میں ایک انوکھا منظر دیکھا تھا۔مریم کی باتیں مجھے اس منظر کی شرح معلوم ہوتی ہیں ۔ میرا خیال ہے کہ محبت صفات سے ہوتی ہوئی ذات کی طرف بڑھتی ہے۔ درست ہے نا آمنہ؟‘‘’’ہاں فہیم! ایک صورت تو یہ ہے کہ محب، محبوب کے احسانات وانعامات کا مشاہدہ کرے۔تسلیم و رضا کو پپہنچے تو یوں صفات سے محبت ہوئی اور دوسری صورت یہ کہ محب انہیں حجاب جانے اور ان کی بہ دولت محبوب کی ذات کو اپنا مقصود و مطلوب ٹھہرائے۔ مجاز میں محبت شے کے ساتھ جب کہ لامجاز میں شے کی لاشے کے ساتھ قرار پکڑتی ہے۔ پہلی نوعیت میں ابہام اور شبہات باقی رہتے ہیں البتہ ادراک نہیں ہوتا لیکن دوسری نوعیت میں اُٹھ جاتے ہیں اور اعتبار بھی مل جاتا ہے‘‘’’وہ چیچک زدہ کُبڑا در یوزہ گر اور اس کے مقابل بیٹھی خوش رُو اور خوش خُودوشیزہ ، جانے وہ کون تھے اور کن زمانوں سے وہاں موجود ہیں ۔ اُن دونوں کی باہمی گفتگو میں میرے لیے اسرار، دانش بھری وابستگی اور جانی پہچانی اپنائیت تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھے؟ تم نے کبھی وہ لَے سنی جو شب کے سناٹوں میں یادن کے سکوت میں سنائی دیا کرتی ہے؟۔۔۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو اس بانسری کا مالک ہے‘‘’’وہ نمائندۂ تشریفات ، وہ کوچہ گرد، وہ درویش اور مختلف بہروپوں والا جو ہمیں مختلف اوقات اور مقامات پر ملتا رہا۔ وہ۔۔۔۔۔ اور وہ دوشیزہ ۔۔۔۔‘‘؟’’ہاں ۔۔۔ ہاں ۔۔۔ وہ کون تھی بھلا؟‘‘’’ہماری بیٹی‘‘’’مریم؟‘‘ میں دوبارہ سانپوں بھرے کنویں میں جاگرا۔ ’’نہیں آمنہ وہ مریم کیسے ہو سکتی ہے۔ کیامیں اُس وقت کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔‘‘؟’’آپ اگر ایک ہی مرد کو مختلف بھید بھاؤ میں دیکھ سکتے ہیں تو مریم کو کیوں نہیں ‘‘’’یہ سلسلہ کب آغاز ہوا؟‘‘’’اُن برسوں میں جب ہم یہاں آکر آباد ہوئے۔ تب مریم بہت چھوٹی تھی۔ ندی پر جب میں کپڑے دھویا کرتی تو یہ میرے پہلوسے لگی رواں پانی پر سنگریز ے اچھالا کرتی اور دُور کے جنگل سے وہ نواسنائی دیا کرتی جسے آپ ’’آوازِ دوست‘‘ سے مشابہ ٹھہرایاکرتے تھے۔
سنگریز ے اچھالنے کا معمول تب تک تھما رہتا جب تک کہ وہ لَے تھم نہ جاتی۔ محبت کا بیج بھی وقت چاہتا ہے ۔ اچانک نہیں اگتا۔ اپنے متعینہ لمحے کا منتظر رہتا ہے ۔ دل کسی گمنام قربت کے انتظار میں مامون رہتا ہے حتیٰ کہ حُب کے تمام مصائب یکے بعد دیگر ے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں ۔ آرزو جو بہت خوشگوار معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے اصل میں بے ثبات ہے اور بے ثبات چیز کبھی جمیل نہیں ہوتی ۔ آپ نے مریم کی آرزو کو دیکھا جو اس کے مقابل تھی۔ جمیل نہ تھی اگرچہ آپ سے جُڑی مقصدیت کا سحر جمیل تھا ۔محبت اصل میں آرزو سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ اس نے شبیہہ کو دیکھا جو تمثیل میں پابند تھی وجود نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے فہیم کہ شبیہہ ہو یا وجود دونوں پابند رہ سکتے ہیں مگر روح نہیں۔‘‘’’اور خانم محبت کے اس قضیئے سے آگاہ ہیں ‘‘’’جی ۔۔۔ اور رہنما بھی وہی ہیں ۔ کیا آپ بھول گئے؟‘‘’’میں کیسے بھلا سکتا ہوں ‘‘ یہ کہتے ہوئے میں نے نظر کے محیط میں آتی کائنات کو دیکھا ۔ مجھے سب سراب معلوم ہُوا۔ خواب محسوس ہُوا۔ لگا ابھی آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہ ہو گا۔ ہست کی کل کہانی عدم کا سایہ ہے اور سائے کو ثبات کہاں۔’’فہیم!‘‘’’جی!‘‘’’آج بزمِ اہل فکر کی محفل بھی ہوگی‘‘’’ہونی تو چاہیے‘‘’’آج بستی کی طرف چلیں گے‘‘’’ہاں جانا تو چاہیے‘‘’’آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے فہیم؟‘‘ایک بھولی بسری دل میں کھُبی ہوئی اَنّی بے اختیار ٹیس بن گئی۔چھُوٹا ہُوا دیار نگاہوں میں گھوم گیا۔ یک لخت اضطرابیت نے گھیر لیا۔ دیرینہ صورتوں کی یاد نے مفلوج کر دیا ہوجیسے۔ پرانی تلخیوں اور صعوبتوں نے جھنجھوڑ دیا ہو جس طرح۔ یتیمی اور تہی دستی کا احساس بھوکے شیروں کی مانند مجھ پر آن جھپٹا۔ سوتیلی نفرتوں اور استحصالیت کی چیونٹیاں بدن پر رینگنے لگیں ۔ ساتھ ساتھ چند مہربان رویوں اور ہمدردیوں کی یاد نے بھی یلغار کی۔ عمرِ رفتہ کا تلاطم اندر ہی اندر اُٹھا تو وجود یوں کپکپانے لگا جیسے بھونچال سے زمین تڑپنے لگتی ہے۔
’’تم نے یاد دلایا تو یا د آگیا‘‘’’اور وہ ڈھلوانی جنگل بھی جس میں سے گزر کر آپ پہلی بار مجھ تک پہنچے تھے۔۔۔
کیا وہ بھی؟‘‘’’ہاں وہ بھی۔۔۔ لیکن آج وہ سب تمہیں کیوں یاد آنے لگا بھئی۔ خیر تو ہے؟‘‘
’’جی چاہتا ہے ایک بار دیکھ لوں ۔ بس آخری بار فہیم۔ صرف ایک دفعہ پھر جانے کو من کرتا ہے،
اُن چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھنا ہے ۔مَیں ان چوبی سیڑھیوں پر بیٹھنا چاہتی ہوں ۔ اپنی ہاتھوں لگائے ہوئے پیڑوں کوچھُونا چاہتی ہوں ۔ اس پیڑ کو جس پر آپ نے اپنی انگشتِ شہادت کے ناخن سے کھرنچ ڈالی تھی اپس کا لمس محسوس کرنا چاہتی ہُوں۔ کچھ دیر اُس گورستان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس میں میرے اجداد خاک اوڑھے سوتے ہیں ۔۔۔ اور پتھر کی ہموار سِلوں پر بیٹھ کر نیچے جنگل کی طرف دیکھوں گی۔ ہم اس جنگل میں کچھ ساعتیں گزاریں گے جس میں خود رَو بیلیں ، چشمے ، پھول ، پرندے ، پگڈنڈیاں اور آزاد طینت جانور تھے۔ بتائیے فہیم کب چلیں گے؟‘‘ "جب تم چاہو۔کہو تو ابھی چلے چلتے ہیں"میں نے جواب دیا۔’’مجھ معاف کر دینا فہیم کہ جو عہد ہم نے مشترکہ باندھا تھا میں ہی اس کی شکنی کی مرتکب ہو رہی ہوں‘‘’’بعض وعدوں اور معاہدوں کا ٹوٹنا بہت اچھا لگتا ہے آمنہ!‘‘’’شکریہ فہیم!‘‘’’اب تکلف تو نہ ہو تو‘‘سورج اس اثناء میں مشرق کی گود سے سر اٹھانے لگا ۔ مریم نے برآمدے کے مرکزی چوبی ستون سے ٹیک لگائے صدا دی۔ ’’صاحبان! ناشتہ آپ دونوں کا منتظر ہے‘‘ہم دونوں ہنسے، اُٹھے اور مریم کی قیادت میں باورچی خانے کی طرف بڑھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۱۰- باب
باہر موسم کی سنگینی عروج پر ہے۔ گھپ تاریکی میں چہارسو پھیلی برف کی سفید چادر چاندنی کا سماں پیدا کرنے لگی ہے اور بادِ سموم کے مشتعل جھکڑاڑیل بھینسوں کی مانند دیواروں اور درختوں سے رگڑ کھا کر گزرتے ہیں ۔ انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں کی شیرِ گرم حدت سے مریم کی پیشانی پر دھیمی دھیمی نمی کا غبار ہے۔ میری بچی ، میری مریم ۔۔۔۔ اپنے گاڑھے دکھ سے مضمحل سو رہی ہے جس کے مہلک احساس کی بے دار ی سے قبل مجھے اپنے اس مکتوب کو مکمل کرنا ہوگا۔توہُوا ےُوں کہ اس وعدے کی تکمیل سے پہلے جو میں نے آمنہ سے کیا تھا، بزمِ اہلِ فکر کے سبھی اراکین کے اعزاز میں ایک وداعی دعوتِ طعام کا اہتمام کیا گیا۔ خبر ملنے کی دیر تھی کہ عین وقتِ مقرر ہ پر محبوب لوہار، حکیم نشتر انصاری، نورو ملاح، ماسٹر خوشحال سنگھ، حافظ شمسی، موہن داس سُنار، مائی خیراں اور آنسہ انجیلا آپہنچیں۔ہمارا وہ بزمِ فکر کا آخری اجلاس تھا جس کے باقاعدہ آغاز سے قبل نقیبِ مجلس آمنہ نے حافظ شمسی سے تلاوتِ قرآنِ حکیم کی درخواست کی۔ حافظ صاحب کے کانپتے ، چھچھلتے اور رعشہ زدہ مگرپُر سوز لحن نے ماحول کو عقیدت میں نہلا دیا۔
بعد ازاں انہوں نے بائبل، گرنتھ اور گیتا کے چنیدہ اقتباسات بھی نذرِ سامعین کیے۔ مریم نے رجسٹرکاروائی سنبھالا۔ صدرِ محفل کے لیے نُورو ملاح کا نام تجویز ہوا۔ آمنہ نے کہا:’
’ذی وقار حاضرینِ محفل!۔۔۔۔ خوش آمدید!!!!
آج سے سولہ برس قبل ہم اپنی واماندہ سانسوں کو خرچ کرتے یہاں پہنچے تو وقوعات کی تیز بوچھاڑ میں افتاں و خیزاں زندگی کو عارضی جائے امن ملی تھی۔ ہمیں آپ کی ہم نفسی اور ہمسائیگی کا شرف ملا اور جیون کی وہ مشترکہ مقصدیت جس کا تانابانا ہم نے مِل کر بُنا اس میں شاید ہی کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو یا اس پر کوئی لمحۂ تغافل گزرا ہو۔ اگر چہ کچھ لغویات کسی آسیب کی طرح کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ ہماری حیثیت تاحال ایک راہ رُو کی سی ہے کیوں کہ فہیم اور میرے درمیان ابتدا سے ہی یہ سمجھوتہ طے پاچکا تھا کہ کبھی کہیں مستقل قیام نہ کریں گے ۔ ہم جو اتنا عرصہ آ پ کے ساتھ اور آپ کے درمیان رہے تو ایک مقصدیت کے عوض۔۔۔ تاہم جلد ہی اپنے سلوک ،کردار‘ اور بُرے یا بھلے اطوار کی یادوں کا اثاثہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے ۔ہر کہیں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ ہم ایک امید وصل کو ہمیشہ اپنے زادِ راہ میں ساتھ رکھیں گے۔ ممکن ہے ہم کبھی لوٹ سکیں ۔ بہت ممکن ہے کبھی اپنی محبتوں کا دم بھرنے کو پھر پلٹ سکیں۔ ۔۔۔ اس لیے کہ ہم ان کہکشانی راہوں کو علامات لاموہوم جانتے ہیں جو اس بستی تک پہنچتی ہیں ۔ ہم اس کے باسیوں کی آنکھوں میں بے کراں انسیت اور مروت کی عمیق سرخی کو بارِ دگر دیکھنے کی ہمک سے سرشار رہیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں اتر آنے والی اشکوں کی چکا چوند۔۔۔ ہمیں اس زحمت کے بدلے در گزر کیجئے جو آپ کو نہیں اٹھانی چاہیے لیکن ۔۔۔۔‘‘ اور آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔اس ساعتِ گریہ کو بھی آخر کار آنا ہی تھا۔اچھی خاصی شاداں و فرحاں محفل شامِ غریباں میں بدل گئی۔ آنسوؤں ، آہوں اور ہچکیوں نے سارے ماحول کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ کوئی کسی کو دو حرفِ تسلی دینے کے لائق نہ رہا۔
تا دیر یہ کیفیت طاری رہی۔ آنکھیں نہ اٹھ سکیں ۔ سرصدمے سے جھکے رہے۔ جذباتی کشمکش سے بوڑھے وجود کپکپاتے رہے۔ مریم بند رجسٹر کو گھورے جا رہی تھی۔ اس خارجی و باطنی طلاطم کو ضابطۂ تحریر میں لانا امرِ محال تھا۔ بالآخر میرِ محفل نورو ملاح کچھ سنبھلے۔ رُندھے ہوئے لہجے اور اکھڑی سانسوں میں گویا ہوئے:’’سجنو! گو بات دکھ والی ہے مگر مان لو کہ جن کواڑوں کو بند ہونا ہے، ہو کے رہیں گے۔ جیون نام ہی اپنے ادھڑے پن کو مسلسل سیئے جانے کا ہے۔ ہم کسی نہ کسی طور ایک بے ہنگم دھن کی طرح بجتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن اس سمفنی میں جاملتے ہیں جسے موت کہا جاتا ہے۔ پھر بھی ایک عارضی بنیاد پر مستقل عمارت کی حرص سے کبھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ تعلق چاہے کسی بھی فانی اور مادی شے کا ہو، دائمی نہیں رہتا۔ دنیا سب دھوکہ ہے۔ بھرے میلے اور آباد بازار دراصل خواب کی طرح ہیں ۔ آنکھ کھلے تو غائب ۔ میرے مرشد ایک حکایت سنایا کرتے تھے کہ کوئی درویش بازار میں بیٹھا تھا۔ کسی شناسا کا گزر ہوا تو پوچھا۔ ’’خیریت؟‘‘ درویش نے جواب دیا۔ ’’بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں ۔ اللہ تو مانتا ہے بندے نہیں مان رہے‘‘ اور کچھ مدت بعد وہی درویش ایک قبرستان میں بیٹھا تھا کہ اسی دیرینہ شناسا کا گزر ہوا۔ پوچھا ’’خیریت؟‘‘ درویش رونے لگا اور بولا: ’’اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ بندے تو مانتے ہیں ۔ اب اللہ نہیں مان رہا‘‘ کتنا نادان ہے انسان کہ جس شے نے باقی ہی نہیں رہنا اس پر اپنا استحقاق جمانے بیٹھ جاتا ہے ۔ مسافر، سرائے کو ہی منزل سمجھنے لگے تو کہیئے کیا سفر جاری رہ سکتا ہے؟ ۔۔۔ نہیں نا؟ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رشتے ناطوں کے کاروان گزر گئے۔ میں آج اسی برس کا ہوں۔ ایک دن میری ہی ناؤ پہ سوار یہ تینوں یہاں پہنچے اور یہاں قیام کا قصد کیا تو میں جان گیا کہ ہمارے ٹاٹ کے لباسوں میں یہ مخملی پیوند زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ یہ اپنی کہکشان سے بچھڑے وہ ستارے ہیں جن کی مسافت نا تمام ہے۔ کچھ دیر کا ساتھ ہے۔ ان کی آمد سے وادی کی بنیادوں میں دبی ہوئی گم شدہ مسکراہٹوں اور مسرتوں نے سر ابھارے اور مدتوں کی یکسانیت خوردہ زندگیوں نے تبدیلی کی کروٹ لی۔ یہ ہمارے قصبے کی شہ سرخی بن گئے۔ ہم پہلے اپنے اپنے انفرادی معمولات میں غرق تھے۔ یہی تھے جنہوں نے ہمسائیگی اور ہم نفسی کی سعادتوں سے روشناس کیا۔ ہم پر ہماری مخفی صلاحیتوں کا انکشاف کیا۔ کون جانتا تھا کہ محبوب لوہار ایک شاعر، حکیم انصاری انشاء پر داز اور انجیلا قصہ گو ہیں ۔ مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے ۔ میں فرداً فرداً سب کو دعوت کلام دوں گا۔ آج کوئی متعین موضوع نہیں ہے۔ جو جس پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، کر سکتا ہے ۔
پہلے محبوب صاحب آپ!۔۔۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟‘‘۔محبوب پہلے جھینپ گئے کہ طبعاً شرمیلے واقع ہوئے تھے پھر اپنے نیلے رنگ کے صافے سے اپنی نم آنکھوں کو خشک کیا۔ ہولے سے کھنکارے اور ساری محفل پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور چندھیائی ہوئی نظر نچھاور کر کے بولے:’’شکریہ!۔۔۔۔ میرِ مجلس۔۔۔! آپ نے عزت دی۔ مجھے شاعر کہا۔سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ۔ ساری عمر تو لوہا کُوٹتے اور آپ لوگوں کی چارپائیوں، کرسیوں ، میزوں اور پیڑھیوں کی چولیں بٹھاتے گزر گئی۔ میں ایک کھنڈر تھا۔ مجھے تو ان تینوں نے دریافت کیا۔ ایک مدت انحرافات میں گزری اوربقیہ سراسر تسلیمات میں گزر رہی ہے۔ جو ہر شناس یہ سامنے بیٹھے ہیں ۔ اب دریافت شدہ اپنے دریافت کنند گان کے سامنے کیا کہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا۔ بہت تمنا تھی بچوں کی۔خدا نے پوری کر دی۔ آمنہ اور فہیم نے مجھے حقیقی با پ کی طرح عزت دی۔۔۔۔ اور ایسی عزت کہ سگی اولاد ہوتی تو کبھی نہ دے سکتی۔ خدا نے میر ی آرزو کا سُود بھی مجھے عطا کیا۔ مریم کی صورت میں ۔ میں بہت خوش جیتا آرہا تھا۔۔۔ مگر ۔۔۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے ۔ آپ نے بجا فرمایا کہ تعلق کسی بھی شے سے ہو، دائمی نہیں رہتا۔ ماسٹر خوشحال سنگھ میرا بچپن کا بیلی، اس کے پانچ بیٹے اسے جیتے جی چھوڑ گئے۔ وہ پھر بھی زندہ ہے۔ ہم سے زیادہ ہنستا اور قہقہے اڑاتا ہے۔ ۔۔۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح ۔۔۔۔۔‘‘محبوب لوہارنے ساری محفل کی طرف سے منہ پھیر لیااور سب اس کے تھرتھراتے ، جھٹکے کھاتے اور ہلکورے لیتے وجود کو بے بسی سے دیکھنے لگے ۔ میرمجلس نے اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ جمائے اور اپنے گریبان میں جھانکنے لگے۔ ماسٹر خوشحال سنگھ دریدہ مسکراہٹ سمیت محبوب لوہار کی پیٹھ سہلانے لگے۔ محفل کو قدرے قرار آیا تو میرِ مجلس نے آنسہ انجیلا کی جانب دیکھا اور سر کی خفیف سے جنبش سے انہیں سے انہیں بہ زبانِ خاموشی دعوتِ گفتگو دی۔ انجیلا کا گورا چٹا جھریوں بھرا چہرہ کسی باطنی جذبے کی یورش سے پہلے دمکا پھر سنجیدگی کے تیوروں سے مدہم پڑ گیا ۔ انہوں نے کچھ کہنے کو لب واکیے ہی تھے کہ رک گئیں اور اس عالم میں ان کا منہ کچھ ثانیے کو کھلا رہ گیا۔ فوراً ہی انہوں نے اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ کہنے لگیں :’’موضوع تو میرِ مجلس خود بخود طے ہو گیا یعنی ٹرمینل ڈیپروائیویشن ۔۔۔۔ میری مراد ’یقینی ہجرت‘ سے ہے۔ بہت کٹھن موڑ ہے۔ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ سچ بات ہے ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر اس امتحان سے بھی کبھی گزرے گی۔کوئی ساٹھ پینسٹھ برس قبل ہم اطالیہ سے یہاں پہنچے۔ میں ، میری ماں کیپریکااور میرے والد سیموئل جو ایک مشنری تھے۔ اُس وقت میں نوخیز تھی اور والدین کی کڑی تربیت اور تعلیمات کی بہ دولت نن بننے کی آرزو مند تھی۔ جانتے ہیں نا آپ کہ اس بستی کے شمالی سرے پر، ندی کے کنارے جو بڑی کھگر نما چٹان ہے۔ اس کے پاس ہی بہت خوبصورت لکڑی اور پتھروں سے تعمیر کردہ گر جا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس بستی میں مخلوط نسلوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی کثیرتعداد آباد تھی۔ ہندو سکھ اور مسلمانوں کے علاوہ مٹھی بھر بدھ مت والے بھی مگر نہ زبان کے جھگڑے، نہ مذہب کے نام پر فسادات اور نہ ہی نسلی امتیاز کے بکھیڑے تھے۔ ہم نے بہت تھوڑے عرصے میں یہاں کی مقامی بولی کے لب و لہجے پرعبور حاصل کر لیا۔ میری ماں حمل سے تھیں ۔ یہاں پہنچنے کے ٹھیک سات ماہ بعد وہ زچگی کے دوران ہی فوت ہو گئیں ۔ اس صدمے نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا۔ اس کیفیت سے نکلنے میں بہت دیر لگی۔ بہرحال معمولات بحال ہو ہی گئے۔ کوئی سال بھر گزرا کہ تقسیم کی خبریں آنے لگیں ۔ سینتالیس (1947) آیا اور گزر گیا۔ بستی کی بیشتر ہندو آبادی ہجرت کر گئی۔ بہت سے سکھ اور عیسائی خاندان بھی چلے گئے ۔ گرجے میں عبادت کے لیے صرف تین لوگ رہ گئے۔ ہم باپ
بیٹی کے علاوہ تیسرا ینگلو انڈین سمپسن ناصر جو ایک محبوط الحواس شخص تھا۔ وہ کچھ عرصہ تو باقاعدگی سے آتا اور تمام مذہبی امور میں حصہ لیتا رہا پھر اچانک وہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک کوئی خبر نہیں ملی ۔ میرے والد مزید پانچ سال اور جیئے ۔ بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک دن طبیب سے دوا لینے گئے اور ندی پار کے جنگل کی دوسری جانب بڑے قصبے سے واپس لوٹ رہے تھے کہ گرے اور دم توڑ دیا۔ ان کی قبر قصبے کے گرجے کے احاطے میں واقع ہے ۔جب کوئی ہم مذہب نہ رہا تو میرے سامنے دو راستے رہ گئے ۔ یا تو اپنے وطن لوٹ جاؤں یا پھر۔۔۔۔ میں نے ڈگر بدلی۔ درس و تدریس کا انتخاب کیا ۔گرجا چھوڑا اور اپنی منہ بولی بہن جو ہمارے درمیان موجود ہیں ۔ مائی خیراں کے ہاں اُٹھ آئی۔ شادی نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ویسا ملا ہی نہیں جیسا من چاہتا تھا اور اب کوئی حسرت یا خلش بھی نہیں ۔ دل کو آرزو سے بے نیاز ہوئے زمانے گزر گئے۔ البتہ ایک طلب ضرور ہے۔ وہ یہ کہ موت آئے تو میری آنکھیں مکہ اور مدینہ کی زیارت سے سیراب ہوں ۔ دیکھ رہی ہوں کہ آپ چونک اٹھے ہیں ۔ دل تھام کے میرا اعتراف سن لیجئے۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں ۔ اس انقلاب کی ساری تفصیل نہ بتا پاؤں گی۔ یہ جو مریم ہے۔۔۔۔ میں اس کی معلمہ ہوں۔ ۔ میں اس کی غیر معمولی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئی اور چاہا کہ اسے اپنی راہ یعنی جادۂ تثلیث پر چلاؤں۔ میں نے کوشش کی لیکن اس بچی کے حیران کن سوالوں نے مجھے متفکر اور ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ چیلنج دے دیا اس نے ۔تحقیق اور جستجو کی طرف موڑ دیا مجھے۔ میں نے دستیاب سارے پیمانے برتے۔ ساری دلیلیں اور دعوے بے بس ہو گئے۔ میں لاجواب ہو گئی۔ تسلیم کی خُو مجھے ورثے میں ملی ہے۔ نسلی اعلیٰ ظرفی سے محروم نہیں ہوں ۔ لہٰذا میں نے کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ میرے ہاتھ ایک نتیجہ آیا کہ عقیدۂ تثلیث ہر گز الہامی نہیں ہے۔ یہ وہ معمہ اور گورکھ دھندہ ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہ گمراہ کن انسانی دماغوں کی خیانت کا شاخسانہ ہے۔ جس رات میں فیصلہ کر کے سوئی کہ اب خدائے واحد کی بادشاہی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گی تو اسی رات ایک باوقار اور حسین و جمیل خاتون میرے خواب میں آئیں ۔ بے پناہ محبت سے ملیں ۔ مبارک باد دی اور میرا نیا نام تجویز کیا۔ صبح خدیجہ بیدار ہوئی تو انجیلا مر چکی تھی۔۔۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں ۔۔۔۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پاؤں گی‘‘
خدیجہ اپنے آخری الفاظ کے اختتام کے ساتھ ہی اٹھیں اور آہستہ قدموں چلتی ہوئی پہلے مریم کو گلے لگایا اور پھر آمنہ سے آلپٹیں ۔ مجھ سمیت باقی مرد اراکین ششدر بیٹھے اس نئی صورتحال کو مضطرب انداز میں دیکھتے رہ گئے۔ میرِ مجلس نے مسکرا کر خدیجہ کی جانب دیکھا اور ایک اطمینان بھری آہ کھینچ کر بولے:’’جنابِ اقبالؒ فرما گئے:کہہ گئی رازِ محبت پردہ داری ہائے شوقتھی فغاں وہ بھی جسے ضبطِ فغاں سمجھا تھا میں بہت مبارک ہو خدیجہ بہن!۔۔۔ اور نہایت خراجِ تحسین اس بچی مریم کے لیے ۔ میں محض ناؤ ہی چلاتا رہ گیا اور بازی لے گئی یہ چھوٹی سی لڑکی۔ سچ کہا کہنے والے نے کہعشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہّ تماماس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں اور اب بھائی موہن داس جی! آپ کچھ فرمانا چاہیں گے ؟‘‘کسی گمبھیرتا سے ہڑ بڑا کر موہن داس نکلے، سنبھلے اور سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرکر گویا ہوئے:’’اجی میرِ مجلس! فرمائیں وہ جن کے مرتبے بلند ہیں ۔ میں جاتی کا شودر، کہاں میری مجال کہ آپ جیسے مہان بُدھی والوں کے سامنے اپنے چھوٹے منہ سے بڑے بول کہوں۔ ابھی جوآپ نے مہاشے اقبال جی کے اشلوک سنائے ۔تھے تو وہ بھی جاتی کے برہمن پر مزاج کے گو تم ۔۔۔ جنھوں نے اپنے دھرم اور دیس واسیوں کو گوتم کی طرح سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا اور ہمت جگائی۔ میں جانوں کہ مرگ سے سوال کرنے کا گُر جیون کی سوچ سے ہی آیا۔ ہماری جاتی نے اونچے استھان والے برہمنوں کے ہاتھوں بہت کشٹ سہے۔ ہم پر ہر اچھی بات اور ان مول شبد کے لیے دروازے بند تھے۔ پرنتو لمبی کتھا ہے سرکار! چند بولوں میں کہاں نبٹے گی۔ ’رِگ وید‘ میں لکھاہے، جب انسان من کے لوبھ سے مُکتائی پالے تو کل پہر یہی سوچنے لگتا ہے کہ وہ کون ہے، کیوں ہے اور کہاں سے آیا؟ ایک سمے تک میں خود نہ سمجھ پایا کہ آدمی چلتا ہے یا راستہ؟ میں نے سارے دھرموں کے بارے بہت بچا رکیا ۔ کھوج کی۔ ’مرکچھ کٹک‘ کا فسش بھکشو کہتا تھا کہ سر اور منہ کا منڈوانا تب تک اکارت ہے جب تک من کو نہیں منڈوایا میں مانوں کہ شروع میں سب ایک تھا۔ یہ بھید بھاؤ کا پاکھنڈ نہیں تھا۔ بعد میں تو پیٹ پوجا اورللک لوبھ کے کارن ہُوا۔ قرآن شریف میں ہے ۔ جب موسیٰ ؑ جنمے تو ان کی دائی نے فرعون کے خوف سے انہیں جل میں بہا دیا مگر ایشور کے کام نرالے ، ان ہی کے دشمن سے رکھشا کرائی۔۔ اور سر ی کرشن جب یشودھر اکی گود سے نکل کر ندی کے حوالے ہوئے تو کنس سے مہان شکتیوں نے انہیں بچایا۔لیکن یہ بھید اُن ےُگوں میں کب ہماری جاتی کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکتے تھے۔ ک
وئی ظلم سا ظلم تھا۔ کسی کول ، بھیل یا دراوڑ جات کا شودر گائتری اچارن کرتے کسی پنڈت کے قریب سے بھلے خطا سے ہی سہی گزر جاتا تو انچھر اور بھگوان کی سمرن کے کارن وہ کیا کہتے ہیں ۔۔۔۔پاپ کا بھگتان بھرنا لازم تھا۔ بھدرپرش دیوتا سمان گورو کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیتے تھے۔ ملکوتی منتروں کو سننے کی یہ کم سے کم سزاتھی۔ پرنتو آج لائبریریاں بھری پڑی ہیں اور بھگوان کی کرپا سے جس بستی میں فہیم ، آمنہ اور مریم بٹیا جیسی سندر سروپوں کا ساتھ ہو تو جیون آپوں آپ سپھل ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو پریم ہی پریم ہیں ۔ ان کے انگ انگ میں سیندور کی رچنا ہے۔ یہ جان کر من بہت بے کل ہے کہ یہ کسی اور جگ کی یاترا پرتُلے بیٹھے ہیں ۔ اپنی جاتی کے مقدر میں تو ہمیشہ کا کشٹ لکھا ہے۔ ایک اور کشٹ سے پالا پڑ گیا تو کیا پرواہ۔ مکتی تو ملتے ملتے ہی ملے گی۔۔۔ ہمارا کام تو دعا دیئے جانا ہے۔ جہاں رہیں ، سکھی رہیں ۔
بس سرکار! اور کچھ نہیں کہنا مجھے۔ پہلے ہی بہت سمے لے لیا‘‘موہن داس کے بعد میرِ مجلس نے ساری محفل پر ایک اچٹتی ہوئی طاہرانہ نگہ دوڑائی اور حکیم نشتر انصاری پر ٹھہرا کر تبسم فرمایا۔ بولے تو لہجے میں چھیڑنے والی ظرافت عیاں تھی:’’بھائی انصاری! آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ۔۔۔؟‘‘’’انصاری اگر پتھر ہوتا تو تب بھی بول پڑتا کیونکہ جس ادا سے آپ پوچھتے ہیں ، وہ ادا ہی کچھ اور ہے‘‘ حکیم صاحب بے باک واقع ہوئے تھے۔ میرِ مجلس کو جواب دے کر انہوں نے چٹکی بھر سونف پھانکے۔
ناک کی پھننگ تک آئی ہوئی عینک کے اوپر سے ناقدانہ طور پر جائزہ لیا۔ پیٹ کے زور پر اپنی شہرۂ آفاق مختصر ترین ہنسی ہنسے۔ پھسکڑا مارے بیٹھے تھے لٰہذا اسی طرح بیٹھے بیٹھے آگے پیچھے ہلے۔ بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو زور زور سے تھپتھپایا اور مزیدبولنے پر آگئے:’’آج جو کچھ سنا اور دیکھا وہ رائیگاں جانے کے لائق نہیں۔ کیوں کہ آج وہ بھید بھاؤ آشکار ہوئے جو نہ ہوتے تو میرا زُعم ناخالص ہی رہتا جسے میں خالص سمجھتا آیا ہوں کہ اپنے قریب کے ہم نفسوں سے میری جڑت بہت گہری ہے۔۔۔ بہت کچھ میں نے بہت غور سے سنا۔ جس سے اختلاف یا اتفاق کا مجھے حق حاصل ہے۔
چند باتیں میں اپنی من مرضی کی بھی کہنا چاہتا ہوں۔۔۔ عموماً یہ تصور ہے کہ زندگی کے کھیل کے سارے اصول پہلے سے طے شدہ ہیں ۔ واقعات اور حادثات کا ہونا کوئی المیہ نہیں بل کہ مقدر کے اٹل قاعدے کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مخصوص زماں اور مکاں کے چوکھٹے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہماری تمنائیں، جذبات اور تجربات ہمارے انفرادی اور ذاتی فیصلوں کے تابع نہیں ہیں ۔ اس لیے کہ ہمارے فیصلے بھی تقدیر کے پابند ہیں ۔ یعنی موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں ۔۔۔ مگر۔۔۔ میرِ مجلس! مجھے کچھ تلخ نوائی سے معاف رکھیئے گا۔ مجھے نہ کسی کے عقائد سے کوئی نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو میرے عقائد سے ۔
میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو زندان ئتقدیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سب کچھ ہی طے شدہ ہے تو انسانی محنت و مشقت سے کوئی فائدہ؟ عذاب و ثواب کے بحث مباحثوں سے کچھ حاصل؟ رجائیت اور قنوطیت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت؟۔۔۔۔خواہ مخواہ عشق و سرمستی کے نعرے لگانے کی کوئی منطق؟۔۔۔ کوئی ہو تو ہو، میں ایسی شرط اور قید کاقائل نہیں۔۔ میں اپنے شوق سے اس دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی ہنسی خوشی یاروتے بسورتے جانے میں میری مرضی کا کوئی دخل ہوگا۔ زندگی کے سیاق و سباق اور پیش منظر وپسِ منظر میں انسانی منشاء کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ پھر میں محدود اختیار پر کیوں اکتفا کروں جس پر آپ سب شاکر و صابر ہوئے بیٹھے ہیں ۔ ۔۔ میں کیوں کسی ایسے آفاقی منصوبے کا کل پرزہ بنوں جس سے نہ میں پہلے آگاہ تھا اور نہ اب ہوں ۔ یہ عجیب منصوبہ ہے جس میں نہ مجھے میری پسند کے ماں باپ ملے، نہ بیوی ملی اور نہ ہی اولاد ۔ یہ کوئی سلیقہ ہے جینے کا کہ پہلے ہر کوئی میری اصلاح کرتا تھا اور اب میں دوسروں کی اصلاح کرتا پھروں۔ تخلیق کی اس ساری کہانی میں میرا کردار بہت ناگوار ہے۔ میرا آہنگ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جو کائناتی چار دیواری سے باہر لے جانے میں میری رہنمائی کر سکتا ہو؟ ۔۔۔ کسی کے پاس نہیں ہے ۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں فرار ہو جاتا۔ سب اپنے اپنے کھونٹوں سے بندھے جگالی کر رہے ہیں ۔ افسوس میں ایسی موت مارا جاؤں گا جو میرے مطلب کی ہر گز نہیں ہو گی۔‘‘حکیم صاحب ذرا دم لینے کو رکے۔ چند گھونٹ پانی پیا اور اپنی شیروانی کی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ محفل میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی توکانوں کے پردے پھٹ جاتے۔
جلد ہی انہیں اپنا گوہرِ مقصود مل گیا۔ گول سی ڈبیہ سے چٹکی بھر سونف پھانکنے کے بعد انہوں نے وہی پیٹ کے زور پر ہنسی ہنسنے کا معمول دہرایا اور ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑ کر بولے:’’میرِمجلس! آپ سمیت سبھی مجھ پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ میں کیا بکواس کئے جا رہا ہوں۔ مگر آپ میری مراد کو نہیں پار ہے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ ہر گز مذہب کی تخفیف یا خدا کی تکذیب کی رُو سے نہیں کہا۔ میرا اشارہ اس جوہرِ نایاب کی طرف ہے جو علوم اور تہذیب کے فروغ کے لیے از بس لازم ہے۔ مجھے مذہب سے کوئی گلہ نہیں چاہے یہ مخاصمت ہو سکتی ہے چاہے وہ انسان کی جرأت تدبیر سے خوش ہو یا ضبط کر دے۔ دراصل اپنے مؤقف کا اظہار سیدھے سادے طریقے سے کردیا جائے تو توجہ کا رض زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ سواپنا یہ خانہ ساز حربہ ہے کہ پہلے طیش دلاؤ پھر عیش کراؤ" اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب نے زور کا قہقہہ لگایا اور ساری محفل نے سکون کا سانس لیا۔ شام کے سائے ان کی عینک کے شیشوں میں جھانکنے لگے تھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔